ان کے علاوہ احادیث میں اور بھی بعض اعمال کاذکر آیا ہے جیسا کہ کوئی درخت لگادینا یا نہر جاری کر دینا، جن کو علامہ سُیُوطی ؒ نے جمع کرکے گیارہ چیزیں بتائی ہیں، اور ابنِ عِماد ؒ نے تیرہ چیزیں گنوائی ہیں، لیکن ان میں سے اکثر انھی تین کی طرف راجع ہو جاتی ہیں، جیسا کہ درخت لگانا یا نہر جاری کرنا صدقۂ جاریہ میں داخل ہے۔ (عون المعبود)
۲۰۔ عَنْ عَائِشَۃَ ؓ: أَنَّھُمْ ذَبَحُوْا شَاۃً فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَا بَقِيَ مِنْھَا؟ قَالَتْ: مَا بَقِيَ مِنْھَا إِلاَّ کَتِفُھَا۔ قَالَ: بَقِيَ کُلُّھَا إِلاَّ کَتِفُھَا۔
حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ گھر کے آدمیوں نے یا صحابۂ کرام ? نے ایک بکری ذبح کی۔ (اور اس میں سے تقسیم کر دیا) حضورﷺ نے دریافت فرمایا کہ کتنا باقی رہا؟ حضرت عائشہؓ نے عرض کیا کہ صرف ایک شانہ باقی رہ گیا۔
مقصد یہ ہے کہ جو اللہ کے لیے خرچ کر دیا گیا وہ حقیقت میں باقی ہے کہ اس کا دائمی ثواب باقی ہے۔ اور جو رہ گیا وہ فانی ہے، نہ معلوم باقی رہنے والی جگہ خرچ ہو یا نہ ہو۔ صاحبِ ’’مظاہر‘‘ کہتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے اللہ کے اس پاک ارشاد کی طرف
جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا (چاہے اس کے زوال سے ہو یا تمہاری موت سے) اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔
ایک حدیث میں حضورِ اقدسﷺکا پاک ارشاد وارد ہوا ہے کہ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ اس کے سوا دوسری بات نہیں ہے کہ اس کامال وہ ہے جو کھا کر ختم کر دیا، یا پہن کر پرانا کر دیا، یا اللہ کے راستے میں خرچ کرکے اپنے لیے ذخیرہ بنا لیا، اور اس کے علاوہ جو رہ گیا وہ جانے والی چیز ہے جس کو وہ لوگوں کے لیے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ (مسلم)
ایک اور حدیث میں ہے حضورِ اقدسﷺ نے ایک مرتبہ صحابۂ کرام?سے دریافت فرمایا کہ تم میں سے کون شخص ایسا ہے جس کو اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو؟ صحابہ نے عرض کیا: یارسول اللہ! ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے، ہر شخص کو اپنا مال زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ حضورﷺ نے فرمایا کہ آدمی کا اپنامال وہ ہے جس کو (ذخیرہ بنا کر) آگے بھیج دیا اور جو مال چھوڑ گیا وہ وارث کامال ہے۔ (مشکاۃ المصابیح عن البخاری)
ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں حضورِ اقدسﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سور ۂ اَلْھٰکُمُ التَّکَاثُرُتلاوت فرمائی پھر ارشاد فرمایا: آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ او آدمی! تیرے لیے اس کے سوا کچھ نہیں جو کچھ کھا کر ختم کر دے یا پہن کر پرانا کردے یا صدقہ کرکے آگے چلتا کر دے تاکہ اللہ کے خزانہ میں محفوظ رہے۔ (مشکاۃ المصابیح عن مسلم)
متعدد صحابۂ کرام? سے اس قسم کے مضامین کی روایتیں نقل کی گئیں۔ لوگوں کو دنیا کے بینک میں روپیہ جمع کرانے کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، لیکن وہی کیا ساتھ رہنے والا ہے۔ اگر اپنی زندگی ہی میں اس پر کوئی آفت نہ بھی آئے تو مرنے کے بعد بہرحال وہ اپنے کام آنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ کے بینک میں جمع کیا ہوا روپیہ ہمیشہ کام آنے والا ہے۔ نہ اس پر کوئی آفت ہے نہ زوال۔ اور مزید برآں کہ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔
حضرت سہل بن عبداللہ تُستَری ؒ اپنے مال کو اللہ کے راستہ میں بڑی کثرت سے خرچ کرتے تھے۔ ان کی والدہ اور بھائیوں نے حضرت عبداللہ بن مبارک ؒ سے اس کی شکایت کی کہ یہ سب کچھ خرچ کرنا چاہتے ہیں ہمیں ڈر ہے کہ یہ چند روز میں فقیر ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک ؒ نے حضرت سہل ؒ سے دریافت کیا۔ انھوں نے فرمایا کہ آپ ہی بتائیں کہ اگر کوئی مدینہ طیبہ کا رہنے والا رُستاق میں (جو ملکِ فارس کا ایک شہر ہے) زمین خرید لے اور وہاں منتقل ہوناچاہے، وہ مدینہ طیبہ میں اپنی کوئی چیز چھوڑے گا؟ انھوں نے فرمایا کہ نہیں۔ کہنے لگے: بس یہی بات ہے۔ لوگوں کو ان کے جواب سے یہ خیال ہوگیا کہ وہ دوسری جگہ انتقالِ آبادی کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ (تنبیہ الغافلین)
اوران کی غرض دوسرے عالم کو انتقال تھی، اور آج کل تو ہرشخص کو اس کا ذاتی تجربہ بھی ہے۔ جو لوگ ہند سے پاکستان یا پاکستان سے ہند میں مستقل قیام کی نیت سے انتقالِ آبادی اپنے اختیار سے کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے جانے سے پہلے ہی اپنی جائداد مکانات وغیرہ سب چیزوں کے تبادلہ کی کتنی کوشش کرتے ہیں۔ اور اتنے تبادلہ مکمل نہیں ہوجاتا ساری تکالیف برداشت کرنے کے باوجود انتقالِ آبادی کا ارادہ نہیں کرتے۔ اور جو بلا اختیار جبری طور پر ایک جگہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہوگئے ہیں ان کی حسرت و افسوس کی نہ کوئی انتہا ہے نہ خاتمہ۔ یہی صورت بعینہٖ ہر شخص کی اس عالم سے انتقال کی ہے۔ ابھی تک ہر شخص کواپنے سامان جائداد وغیرہ سب چیز کے انتقال کا اختیار ہے، لیکن جب موت سے جبری انتقال ہوجائے گا سب کچھ اس عالم میں رہ جائے گا اور گویا بحقِ سرکار ضبط ہو جائے گا۔ ابھی وقت ہے کہ سمجھ رکھنے والے اپنے سامان کو دوسرے عالم میں منتقل کرلیں۔
۲۱۔ عَنْ أَبِيْ ھُرَیْرَۃَ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ ﷺ: مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللّٰہِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ فَلْیُکْرِمْ ضَیْفَہُ، وَمَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللّٰہِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ فَلَا َیُوْذِ جَارَہُ، وَمَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللّٰہِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ فَلْیَقُلْ خَیْرًا أَوْ لِیَصْمُتْ۔ وَفِيْ رِوَایَۃٍ بَدْلَ الْجَارِ: وَمَنْ کَانَ یُؤْمِنُ
حضورِ اقدسﷺ کا پاک ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اورآخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے اور اپنے پڑوسی کو نہ ستائے اور زبان سے کوئی بات نکالے توبھلائی کی بات نکالے ورنہ چپ رہے۔ اور دوسری روایت میںہے کہ صلہ رحمی کرے۔
بِاللّٰہِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ فَلْیَصِلْ رَحِمَہُ۔متفق علیہ، کذا في مشکاۃ المصابیح۔
اس حدیثِ پاک میں حضورِ اقدسﷺ نے کئی امور پر تنبیہ فرمائی اور ہر مضمون کو حضورﷺ نے اس ارشاد کے ساتھ ذکر فرمایا کہ ’’جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے ‘‘۔ ترجمہ میں اختصار کی وجہ سے شروع ہی میں ذکر پر اِکتفا کیا گیا۔ ہر ہرجملہ کے ساتھ اس کو ذکر فرمانے سے مقصود ان اُمور کی اہمیت اور تاکید ہے۔ جیسا کوئی شخص اپنی اولاد میں سے کسی کو کہے کہ اگر تو میرا بیٹا ہے تو فلاں کام کر دے۔ مقصد اس تنبیہ سے یہ ہے کہ یہ چیزیں کامل ایمان کے افراد ہیں جو ان کا اہتمام نہ کرے اس کا ایمان بھی کامل نہیں۔ (مظاہرِ حق)
اور اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کے ذکر میں خصوصیت غالبًا اس وجہ سے ہے کہ اللہ پر ایمان بغیر تو آخرت میں کسی نیکی کا کوئی ثواب ہی نہیں، اور اللہ پر ایمان میں آخرت پر ایمان خود آگیا تھا، پھر اس کو خصوصیت سے غالبًا اس لیے ذکر فرمایا کہ یہ تنبیہ اور ثواب کی نیت پر شوق دلانا ہے کہ ان اُمور کا حقیقی بدلہ اور ثواب آخرت کے دن ملے گا، جس دن یہ معلوم ہوگا کہ دنیا کی ذرا ذرا سی چیز اور عمل پر اللہ کے یہاں کتنا کتنا اجر و ثواب ہے۔
اس کے بعد حضورﷺ نے اس حدیثِ پاک میں چارچیزوں پر تنبیہ فرمائی۔ پہلی چیز مہمان کا اِکرام ہے، وہی اس جگہ بندہ کا اس روایت کے ذکر کرنے سے مقصود ہے۔ اس کی توضیح آیندہ حدیث میں آئے گی۔ دوسرا مضمون پڑوسی کو ایذا نہ دینے کے متعلق ہے۔ اس حدیث شریف میں ادنیٰ درجہ کا حکم کیا گیا کہ پڑوسی کو ایذا نہ پہنچائے۔ یہ بہت ہی ادنیٰ درجہ ہے۔ ور نہ روایات میں پڑوسی کے حق کے متعلق بہت زیادہ تاکیدیں وارد ہوئی ہیں۔ شیخین کی بعض روایات میں فَلْیُکْرِمْ جَارَہ وارد ہوا ہے۔ یعنی پڑوسی کا اکرام کرے۔ اور شیخین کی بعض روایات میں فَلْیُحْسِنْ إِلَی جَارِہٖ آیا ہے کہ اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے۔ یعنی جس چیز کا وہ محتاج ہو اس میں اس کی اِعانت کرے ،اس سے برائی کو دفع کرے۔
ایک حدیث میں حضورِ اقدسﷺ کا ارشاد وارد ہوا ہے:جانتے ہو کہ پڑوسی کا کیا حق ہے ؟ اگر وہ تجھ سے مدد چاہے تو اس کی مدد کر، اگر قرض مانگے تو اس کو قرض دے، اگر محتاج ہو تو اس کی اِعانت کر، اگر بیمار ہو تو عیادت کر، اگر وہ مرجائے تو اس کے جنازہ کے ساتھ جا، اگر اس کو خوشی حاصل ہو تو مبارک باد دے، اگر مصیبت پہنچے تو تعزیت کر، بغیر اس کی اجازت کے اس کے مکان کے پاس اپنا مکان اونچا نہ کر جس سے اس کی ہوا رُک جائے، اگر تو کوئی پھل خریدے تو اس کو بھی ہدیہ دے، اور اگر یہ نہ ہوسکے تو اس پھل کو ایسی طرح پوشیدہ گھر میں لاکہ وہ نہ دیکھے اور اس کو تیری اولاد باہر لے کر نہ نکلے تاکہ پڑوسی کے بچے اس کو دیکھ کررنجیدہ نہ ہوں، اور اپنے گھر کے دھوئیں سے اس کو تکلیف نہ پہنچا مگر اس صورت میں کہ جو پکائے اس میں سے اس کا بھی حصہ لگالے۔ تم جانتے ہو کہ پڑوسی کا کتنا حق ہے؟ قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے! کہ اس کے حق کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا جس پر اللہ رحم کرے۔ روایت کیا اس کو غزالی ؒ نے ’’اربعین‘‘ میں۔ (مظاہرِ حق بتغیُّر) حافظ ابنِ حجر ؒنے ’’فتح الباری‘‘ میں بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔
ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضورِ اقدسﷺ نے (تین مرتبہ) فرمایا: خدا کی قسم! مؤمن نہیں ہے۔ خدا کی قسم! مؤمن نہیں ہے۔ خدا کی قسم! مؤمن نہیں ہے۔ کسی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کون شخص؟ حضورﷺ نے فرمایا: جس کا پڑوسی اس کی مصیبتوں (اور بدیوں) سے مامون نہ ہو۔ (مشکاۃ المصابیح عن الشیخین)
ایک اور حدیث میں ہے کہ جنت میں وہ شخص داخل نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کی مصیبتوں سے مامون نہ ہو۔ حضرت ابنِ عمر اور حضرت عائشہ ? دونوں حضرات حضورِاقدسﷺ کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ حضرت جبرئیل ؑ مجھے پڑوسی کے بارہ میں اس قدر تاکید کرتے رہے کہ مجھے ان کی تاکیدوں سے یہ گمان ہوا کہ پڑوسی کو وارث بنا کررہیں گے۔ (مشکاۃ المصابیح) حق تعالیٰ سبحانہ ٗوتقدس کا پاک ارشاد ہے:
{وَاعْبُدُوْا اللّٰہَ وَلَا تُشْرِکُوْا بِہٖ شَیْئًا وَّبِالْوَالِدَیْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِی الْقُرْبٰی وَالْیَتٰمٰی وَالْمَسٰکِیْنِ وَالْجَارِ ذِی الْقُرْبٰی وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِیْلِ}
تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اختیار کرو، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اور دوسرے اہلِ قرابت کے ساتھ بھی، اور یتیموں کے ساتھ اور غربا کے ساتھ اور پاس والے پڑوسی کے ساتھ بھی اور دور والے پڑوسی کے ساتھ بھی اور ہم مجلس کے ساتھ بھی اور مسافر کے ساتھ بھی۔
’’پاس والے پڑوسی‘‘ سے مراد یہ ہے کہ اس کامکان قریب ہو۔ اور ’’دُور کے پڑوسی‘‘ سے مراد یہ ہے اس کا مکان دُور ہو۔ حسن بصری ؒ سے کسی نے پوچھا کہ پڑوس کہاں تک ہے ؟ انھوں نے فرمایا کہ چالیس مکان آگے کی جانب اور چالیس پیچھے کی جانب، چالیس دائیں اور چالیس بائیں جانب۔
حضرت ابو ہریرہ ؓ سے نقل کیا گیا کہ دور کے پڑوسی سے اِبتدا نہ کی جائے بلکہ پاس کے پڑوسی سے ابتدا کی جائے۔ حضرت عائشہؓ نے حضو رِ اقدسﷺ سے دریافت کیا کہ میرے دو پڑوسی ہیں کس سے ابتدا کرو ں؟ حضورﷺ نے فرمایا: جس کا دروازہ تیرے دروازہ سے قریب ہو۔حضرت ابنِ عباس? سے مختلف طریق سے نقل کیا گیا کہ پاس کاپڑوسی وہ ہے جس سے قرابت ہو اوردور کا پڑوسی وہ ہے جس سے قرابت نہ ہو۔ نوف شامی ؒسے نقل کیا گیا کہ پاس کا پڑوسی مسلمان پڑوسی ہے اور دُور کا پڑوسی یہود و نصاریٰ، یعنی غیر مسلم۔ (دُرِّمنثور)
’’مُسند ِبزّار‘‘ وغیرہ میں حضورِ اقدسﷺ کا پاک ارشاد نقل کیا گیا کہ پڑوسی تین طرح کے ہیں۔ ایک وہ پڑوسی جس کے تین حق ہوں۔ پڑوس کا حق، رشتہ داری کا حق اور اسلام کا حق۔ دوسری قسم وہ ہے جس کے دو حق ہوں۔ پڑوس کا حق اور اسلام کا حق۔ تیسری قسم وہ ہے جس کا ایک ہی حق ہو، وہ غیر مسلم پڑوسی ہے۔ (حاشیۃ الجمل) گویا پڑوس کے تین درجے ترتیب وار ہوگئے۔ امام غزالی ؒ نے بھی اس حدیث شریف کو نقل فرمایا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دیکھو اس حدیث شریف میں محض پڑوسی ہونے کی وجہ سے مشرک کا حق بھی مسلمان پر قائم فرمایا ہے۔
ایک اور حدیث میں حضورِ اقدسﷺ کا ارشاد نقل کیا گیا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے دو پڑوسیوں میں فیصلہ کیا جائے گا۔ ایک شخص حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے پاس آئے اور اپنے پڑوسی کی کثرت سے شکایت کرنے لگے۔ حضرت ابنِ مسعودؓ نے فرمایا جائو (اپنا کام کرو) اگر اس نے تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ شا نہٗ کی نافرمانی کی (کہ تم کو ستایا) تو تم تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ شا نہٗ کی نافرمانی نہ کرو۔
ایک صحیح حدیث میں آیا ہے کہ حضورِ اقدسﷺکی خدمت میں ایک عورت کا حال بیان کیا گیا کہ وہ روزے بھی کثرت سے رکھتی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو ستاتی ہے۔ حضورﷺ نے فرمایا: وہ جہنم میں داخل ہوگی۔ (چاہے پھر سزا بھگت کر نکل آئے) امام غزالی ؒ فرماتے ہیں کہ پڑوسی کا حق صرف یہی نہیں کہ اس کو تکلیف نہ دی جائے، بلکہ اس کاحق یہ ہے کہ اس کی تکلیف کو برداشت کیا جائے۔ حضرت ابنِ المقُفَّع ؒ اپنے پڑوسی کی دیوار کے سایہ میں اکثر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ان کو معلوم ہوا کہ اس کے ذمہ قرض ہوگیا جس کی وجہ سے وہ اپنا گھر فروخت کرنا چاہتا ہے، فرمانے لگے کہ ہم اس کے گھر کے سایہ میں ہمیشہ بیٹھے، اس کے سایہ کا حق ہم نے کچھ ادا نہ کیا۔ یہ کہہ کر اس کے گھر کی قیمت اس کو نذر کر دی اور فرمایا کہ تمہیں قیمت وصول ہوگئی، اب اس کو فروخت کرنے کا ارادہ نہ کرنا۔ حضرت ابنِ عمر? کے غلام نے ایک بکری ذبح کی۔ حضرت ابنِ عمر? نے فرمایا کہ جب اس کی کھال نکال چُکو تو سب سے پہلے اس کے گوشت میں سے میرے یہودی پڑوسی کو دینا۔ کئی دفعہ یہی لفظ فرمایا۔ غلام نے عرض کیا کہ آپ کتنی مرتبہ اس کو فرمائیں گے؟ حضرت ابنِ عمر ? نے فرمایا کہ میں نے حضورِ اقدسﷺ سے سنا وہ فرماتے تھے کہ مجھے حضرت جبرئیل ؑ بار بار پڑوسی کے متعلق تاکید فرماتے رہے۔ (اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں)
حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ مکارمِ اخلاق دس چیزیں ہیں۔ بسا اوقات یہ چیزیں بیٹے میں ہو جاتی ہیں باپ میں نہیں ہوتیں، غلام میں ہو جاتی ہیں آقا میں نہیں ہوتیں، حق تعالیٰ شا نہٗ کی عطا ہے جس کو چاہے عطا کر دیں۔ ۱۔ سچ بولنا ۲۔ لوگوں کے ساتھ سچائی کا معاملہ کرنا(دھوکہ نہ دینا ) ۳۔ سائل کو عطا کرنا ۴۔ احسان کا بدلہ دینا ۵۔ صلہ رحمی کرنا ۶۔امانت کی حفاظت کرنا ۷۔ پڑوسی کا حق ادا کرنا ۸۔ ساتھی کا حق ادا کرنا ۹۔ مہمان کا حق ادا کرنا ۱۰۔ ان سب کی جڑ اور اصلِ اُصول حیا ہے۔ (اِحیاء العلوم)
تیسرا مضمون حدیثِ بالا میں یہ ہے کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ خیر کی بات زبان سے نکالے یا چپ رہے۔ حافظ ابن حجر ؒ فرماتے ہیں کہ حضورﷺ کا یہ پاک ارشاد جامع کلمہ ہے۔ اس لیے کہ جو بات کہی جائے وہ یا خیر ہوگی یا شر۔ اور خیر میں ہر وہ چیز داخل ہے جس کا کہنا مطلوب ہے فرض ہو یا مستحب۔ اس کے علاوہ جو رہ گیا وہ شر ہے۔ (فتح الباری) یعنی اگر کوئی ایسی بات ہو جو بظاہر نہ خیر معلوم ہوتی ہو نہ شر، وہ حافظ ؒ کے کلام کے موافق شر میں داخل ہو جائے گی۔ اس لیے کہ جب کوئی فائدہ اس سے مقصود نہیں تو لغوہوئی، وہ خود شر ہے۔
حضرت اُمِ حبیبہؓ نے حضورِ اقدسﷺ کاارشاد نقل کیا کہ آدمی کا ہر کلام اس پر وبال ہے کوئی نفع دینے والی چیز نہیں، بجز اس کے کہ بھلائی کا حکم کرے یا برائی سے روکے یا اللہ کاذکر کرے۔ اس حدیث کو سن کر ایک شخص کہنے لگے: یہ حدیث تو بڑی سخت ہے۔ حضرت سفیان ثوری ؒ نے فرمایا کہ اس میں حدیث کی سختی کی کیا بات ہے یہ تو خود اللہ نے قرآن شریف میں فرمایا:
{لاَ خَیْرَ فِیْ کَثِیْرٍ مِّنْ نَّجْوٰھُمْ الاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَۃٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ م بَیْنَ النَّاسِط وَمَنْ یَّفْعَلْ ذٰلِکَ ابْتِغَآئَ مَرْضَاتِ اللّٰہِ فَسَوْفَ نُؤْتِیْہِ اَجْرًا عَظِیْمًا o}
لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں خیر نہیں ہوتی، ہاں مگر جو لوگ ایسے ہیں کہ خیرات یا کسی نیک کام کی یا لوگوں میں باہم اصلاح کر دینے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے واسطے یہ کام کرے گا ہم اس کو عن قریب بہت زیادہ اجر عطا کریں گے۔
حضرت ابوذرؓ فرماتے ہیں: میں نے حضورﷺ سے عرض کیا: مجھے کچھ وصیت فرما دیجیے۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اللہ کے خوف کی وصیت کرتا ہوں کہ یہ تمہارے ہر کام کے لیے زینت ہے۔ میں نے عرض کیا: کچھ اور۔ ارشاد فرمایا کہ قرآن شریف کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کا اہتمام کہ جو آسمانوں میں تمہارے ذکر کا سبب ہے اور زمین میں تمہارے لیے نور ہے۔ میں نے اور زیادتی چاہی توارشاد فرمایا کہ سکوت بہت کثرت سے رکھاکرو، یہ شیطان کے دُور رہنے کا ذریعہ ہے اور دینی کاموں میں مددکا سبب ہے۔ میں نے اور زیادتی چاہی تو فرمایا کہ ہنسنے کی زیادتی سے اِحتراز کرو، اس سے دل مر جاتا ہے اور منہ کی رونق کم ہو جاتی ہے۔ میں نے عرض کیا: اور کچھ۔ فرمایا: حق بات کہو چاہے کڑوی ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے عرض کیا: اور کچھ۔ فرمایا: اللہ کے معاملہ میں کسی کا خوف نہ کرو۔ میں نے عرض کیا: اور کچھ۔ فرمایا کہ تمہیں اپنے عیوب (کا فکر) لوگوں کے عیوب کو دیکھنے سے روک دے۔ (دُرِّمنثور)
امام غزالی ؒ فرماتے ہیں کہ زبان اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت اور اس کی غریب و لطیف صنعتوں میں سے ایک صنعت ہے۔اس کا جُثَّہ چھوٹا ہے، لیکن اس کی اِطاعت اور گناہ بہت بڑے ہیں، حتیٰ کہ کفر و اسلام جو گناہ اور اِطاعت میں دو آخری کناروں پر ہیں اسی سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی بہت سی آفتیں شمار کی ہیں۔ بے کار گفتگو، بے ہودہ باتیں، جنگ و جدل، منہ پھیلا کر باتیں کرنا، مقفّٰی عبارتوں اور فصاحت میں تکلف کرنا، فحش بات کرنا، گالی دینا، لعنت کرنا، شعر و شاعری میں اِنہماک، کسی کے ساتھ تمسخر کرنا، کسی کا راز ظاہر کرنا، جھوٹا وعدہ کرنا، جھوٹ بولنا، جھوٹی قسم کھانا، کسی پر تعریض کرنا، تعریض کے طورپرجھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، دو رنگی باتیں کرنا، بے محل کسی کی تعریف کرنا، بے محل سوال کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اتنی کثیر آفتیں اس چھوٹی سی چیز کے ساتھ وابستہ ہیں کہ ان کا مسئلہ نہایت خطرناک ہے۔ اسی وجہ سے حضورِ اقدسﷺ نے چپ رہنے کی بہت ترغیب فرمائی ہے۔ حضورﷺ کا ارشاد ہے کہ جوشخص چپ رہا وہ نجات پاگیا۔
ایک صحابی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے اسلام کے بارہ میں ایسی چیز بتا دیجیے کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے پو چھنا نہ پڑے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ پر ایمان لائو اور اس پر استقامت رکھو۔ انھوں نے عرض کیا: حضور! میں کس چیز سے بچوں؟ حضورﷺ نے فرمایا: اپنی زبان سے۔ ایک اور صحابی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! نجات کی کیا صورت ہے؟ حضورﷺ نے فرمایا کہ اپنی زبان کو روکے رکھو، اپنے گھر میں رہو، (فضول باہر نہ پھرو )اور اپنی خطائوں پر روتے رہو۔ ایک حدیث میں حضورِ اقدسﷺ کا پاک ارشاد نقل کیا گیا کہ جو شخص دو چیزوں کا ذمہ لے لے میں اس کے لیے جنت کا ذمہ دار ہوں۔ ایک زبان دوسری شرم گاہ۔ ایک حدیث میں ہے: حضورِ اقدسﷺ سے سوال کیا گیا کہ جو چیزیں جنت میں داخل کرنے والی ہیں ان میں سب سے اہم کیا چیز ہے؟ حضورﷺ نے فرمایا: اللہ کا خوف اور اچھی عادتیں۔ پھر عرض کیا گیا کہ جہنم میں جو چیزیں داخل کرنے والی ہیں ان میںا ہم چیز کیا ہے؟ حضورﷺنے فرمایا: منہ اور شرم گاہ۔
حضرت عبداللہ بن مسعودؓ صفا و مروہ کی سعی کر رہے تھے اور اپنی زبان کو خطاب کرکے فرماتے تھے: اے زبان! اچھی بات کہہ نفع کمائے گی اور شر سے سکوت کر سلامت رہے گی اس سے پہلے کہ شرمندہ ہو۔ کسی نے پوچھا کہ یہ جو کچھ آپ فرما رہے ہیں اپنی طرف سے فرما رہے ہیں یا آپ نے اس بارہ میں کچھ حضورِ اقدسﷺ سے سنا ہے؟ انھوں نے فرمایا کہ میں نے حضو ر ﷺ سے سنا ہے کہ آدمی کی خطائوں کا اکثر حصہ اس کی زبان میں ہوتا ہے۔
حضرت عبداللہ بن عمر? حضورِ اقدسﷺ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص اپنی زبان کو روکے رہے اللہ اس کی عیب پوشی کرتے ہیں۔ اور جو شخص اپنے غصہ پر قابو رکھے اللہ اس کو اپنے عذاب سے محفوظ فرماتے ہیں۔ اور جو شخص اللہ کی بارگاہ میں معذرت کرتا ہے حق تعالیٰ شا نہٗ اس سے عذر کو قبول فرماتے ہیں۔
حضرت معاذؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے کچھ وصیت فرمائیں۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ اس کو دیکھ رہے ہو اور اپنے آپ کو مُردوں میں شمار کرو اور اگر تم کہو تو میں وہ چیز بتائوں جس سے ان چیزوں پر سب سے زیادہ قدرت حاصل ہو جائے؟ اور یہ فرما کر اپنی زبان کی طرف اشارہ فرمایا۔ (اِحیاء العلوم)
حضرت سلیمان علی نبینا و علیہ السلام سے نقل کیا گیا کہ اگر کلام چاندی ہے تو سکوت سونا ہے۔ حضرت لقمان حکیم ؑ جو اپنی حکمت اور دانائی کی وجہ سے دنیا میں مشہور ہیں ایک حبشی غلام نہایت بدصورت تھے، مگر اپنی حکمتوں کی وجہ سے مقتدائے عالم تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ تُو فلاں شخص کا غلام نہیںہے؟ انھوں نے فرمایا: بیشک ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ تُو فلاں پہاڑ کے نیچے بکریاں نہ چراتا تھا؟ انھوں نے فرمایا: صحیح ہے۔ پھر اس نے کہا کہ پھر یہ مرتبہ کس بات سے ملا؟ انھوں نے فرمایا: (چار چیزوں سے) اللہ کا خوف، بات میں سچائی، امانت کا پورا پورا ادا کرنا اور بے فائدہ بات سے سکوت۔ اور بھی متعدد روایات میں ان کی خصوصی عادت کثرتِ سکوت ذکر کی گئی۔ (دُرِّمنثور)
حضرت براءؓ فرماتے ہیں کہ ایک بَدّو نے آکر عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے ایسا عمل بتا دیجیے جو جنت میں لے جانے والا ہو۔ حضورﷺ نے فرمایا: بھوکے کو کھانا کھلائو، پیاسے کو پانی پلائو، اچھی باتوں کا لوگوں کو حکم کرو اور بری باتوں سے روکو۔ اور یہ نہ ہو سکے تو اپنی زبان کو بھلی بات کے علاوہ بولنے سے روکے رکھو۔ حضورِ اقدسﷺ کاپاک ارشاد ہے کہ اپنی زبان کو خیر کے علاوہ سے محفوظ رکھو کہ اس کے ذریعہ سے تم شیطان پر غالب رہو گے۔
یہ چند روایات مختصراً ذکر کی ہیں۔ ان کے علاوہ بہت سی روایات اور آثار ہیں جن کو امام غزالی ؒ نے ذکر کیا اور علامہ زَبیدی ؒ اور حافظ عراقی ؒ نے ان کی تخریج کی ہے۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ زبان کا مسئلہ اہم مسئلہ ہے جس سے ہم لوگ بالکل غافل ہیں، جو چاہا زبان سے کہہ دیا، حالاںکہ اللہ کے دو نگہبان ہر وقت دن اور رات، دائیں اور بائیں مونڈھوں پر موجود رہتے ہیں، جو ہر بھلائی اور برائی کو لکھتے ہیں۔
اس سب کے بعد اللہ اور اس کے پاک رسولﷺ کا کیا کیا احسان ذکر کیا جائے، آدمی سے بے اِلتفاتی میں فضول بات نکل ہی جاتی ہے، حضورﷺ نے ارشاد فرمایا: کفارہ مجلس کا یہ ہے کہ اٹھنے سے قبل تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لے: سُبْحَانَ اللّٰہِ وَبِحَمْدِہٖ سُبْحَانَکَ اللّٰھُمَّ وَبِحَمْدِکَ أَشْھَدُ أَنْ لَّا إِلٰـہَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُکَ وَأَتُوْبُ إِلَیْک۔ (حصن حصین) ایک حدیث میں ہے کہ حضورِاقدسﷺ اَخیر میں ان کلمات کو پڑھا کرتے تھے، کسی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ پہلے تو ان کلمات کو نہیں پڑھتے تھے۔ حضورﷺ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کلمات مجلس کا کفارہ ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے حضورﷺ نے فرمایا: چند کلمے ایسے ہیں کہ جو شخص مجلس سے اٹھنے کے وقت تین مرتبہ ان کوپڑھے تووہ مجلس کی گفتگو کے لیے کفارہ ہو جاتے ہیں، اور اگر مجلسِ خیر میں پڑھے جائیں تو اس مجلس (کے خیر ہونے) پر ان سے مہر لگ جاتی ہے جیسا کہ خط کے ختم پر مہر لگائی جاتی ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں: سُبْحَانَکَ اللّٰھُمَّ وَبِحَمْدِکَ لَآ إِلٰـہَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُکَ وَأَتُوْبُ إِلَیْکَ۔ (ابوداود)
چوتھا مضمون حدیثِ بالا میں صلہ رحمی کے متعلق ہے، اس کا مفصل بیان آیندہ فصلوں میں آرہا ہے۔
۲۲۔ عَنْ أَبِيْ شُرَیْحٍ الْکَعْبِيِّ ؓ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰہِ ﷺ قَالَ: مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللّٰہِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ فَلْیُکْرِمْ ضَیْفَہُ، جَائِزَتُہُ یَوْمٌ وَلَیْلَۃٌ وَالضِّیَافَۃُ ثَلَاثَۃُ أَیَّامٍ، فَمَا بَعْدَ ذٰلِکَ فَھُوَ صَدَقَۃٌ، وَلاََ یَحِلُّ لَہُ أَنْ یَّثْوِيَ عِنْدَہُ حَتَّی یُحْرِجَہُ۔
حضورِ اقدس ﷺ کا پاک ارشاد ہے کہ جوشخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مہمان کا اِکرام کرے۔ مہمان کا جائزہ ایک دن رات ہے اور مہمانی تین دن رات۔ اور مہمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ اتنا طویل قیام کرے جس سے میزبان مشقت میں پڑجائے۔
اس حدیث شریف میں حضورِ اقدسﷺ نے دو ادب ارشاد فرمائے۔ ایک میزبان کے متعلق اور دوسرا مہمان کے متعلق۔ میزبان کا ادب یہ ہے کہ اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، جیسا کہ پہلی حدیث میں گزر چکا ہے، تو اس کو چاہیے کہ مہمان کا اِکرام کرے۔ اور مہمان کا اکرام یہ ہے کہ کشادہ روئی اور خوش خُلُقی سے پیش آئے، نرمی سے گفتگو کرے۔ (مظاہرِ حق) ایک حدیث میں ہے کہ سنت یہ ہے کہ آدمی مہمان کے ساتھ گھر کے دروازہ تک مشایعت کے لیے جائے۔ (مشکاۃ المصابیح)
حضرت عقبہؓحضورِ اقدسﷺ کاارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص مہمانی نہ کرے اس میں کوئی خیر نہیں۔ حضرت سمرہؓ فرماتے ہیں کہ حضورِ اقدسﷺ مہمان کی ضیافت کا حکم فرمایا کرتے تھے۔(مجمع الزوائد) ایک شخص نے دیکھا کہ حضرت علیؓ رو رہے ہیں، اس نے سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ سات دن سے کوئی مہمان نہیں آیا، مجھے اس کا ڈر ہے کہ کہیں حق تعالیٰ شا نہٗ نے میری اِہانت کا ارادہ تو نہیں کرلیا۔ (اِحیاء العلوم)
حضورِ اقدسﷺ نے حدیثِ بالا میں مہمان کے اِکرام کا حکم فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا ہے کہ اس کا جائزہ ایک دن رات ہے۔ اس کی تفسیر میں علماء کے چند قول ہیں۔ حضرت امام مالک ؒ سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ اس سے مراد اِکرام و اِعزاز اور خصوصی تحفے ہیں۔ یعنی ایک دن رات تو اس کے اِعزاز میں اچھا کھانا تیار کرے اور باقی اَیّام میں معمولی مہمانی۔ اس کے بعد پھر علماء کے اس میں دو قول ہیں کہ تین دن کی مہمانی جو حضورﷺ کے پاک ارشاد میں وارد ہوئی ہے وہ اس ایک دن کے بعد ہے، یعنی مہمان کا حق کل چار دن ہوگئے، یا وہ ایک دن خصوصی اِعزاز کا بھی انھی تین دن میں داخل ہے۔
دوسرا مطلب یہ ہے کہ جائزہ سے مراد ناشتہ ہے راستہ کا۔ اور حاصل یہ ہے کہ اگر مہمان قیام کرے تو تین دن کی مہمانی ہے اور قیام نہ کرسکے تو ایک دن کا ناشتہ۔ (فتح الباری)
چوتھا مطلب یہ ہے کہ جائزہ سے مراد گزر ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ جو شخص مستقل ملاقات کے لیے آئے اس کا حق تین دن قیام کا ہے اور جو راستہ میں گزرتے ہوئے ٹھہر جائے کہ اصل مقصود آگے جانا تھا یہ جگہ راستہ میں پڑگئی، اس لیے یہاں بھی قیام کرلیا، تو اس کے قیام کا حق صرف ایک دن ہے۔ (الترغیب والترہیب)
اور ان سب اقوال کا خلاصہ مختلف حیثیت سے مہمان کے اِکرام کا اہتمام ہی ہے کہ ایک دن کا اس کا خصوصی اہتمام کھانے کا کرے اور روانگی کے وقت ناشتہ کا بھی بالخصوص ایسے راستوں میں جہاں راستہ میں کھانا نہ مل سکتا ہو۔
دوسرا اَدب حدیثِ بالا میں مہمان کے لیے ہے کہ کہیں جاکر اتنا طویل قیام نہ کرے جس سے میزبان کو تنگی اور دِقّت پیش آئے۔ ایک اور حدیث میں اس لفظ کی جگہ یہ اِرشاد ہے کہ اتنا نہ ٹھہرے کہ میزبان کو گناہ گار بنا دے۔ یعنی یہ کہ اس کے طویل قیام کی وجہ سے میزبان اس کی غیبت کرنے لگے یا کوئی ایسی حرکت کرے جس سے مہمان کو اَذیت ہو یا مہمان کے ساتھ کسی قسم کی بدگمانی کرنے لگے کہ یہ سب اُمور میزبان کو گناہ گار بنانے والے ہیں، لیکن یہ سب کچھ اس صورت میں ہے کہ میزبان کی طرف سے مہمان کے قیام پر اِصرار اور تقاضا نہ ہو یا اس کے اندازسے غالب گمان یہ ہو کہ زیادہ قیام اس پر گراں نہیں ہے۔
ایک حدیث میں ہے: کسی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا چیز ہے جو اس کو گناہ میں ڈالے؟ حضورﷺ نے فرمایا: اس کے پاس اتنا قیام کرے کہ میزبان کے پاس اس کے کھلانے کو کچھ نہ ہو۔ حافظ ؒ کہتے ہیں کہ اس میں حضرت سلمانؓ کا اپنے مہمان کے ساتھ ایک قصہ پیش آیا۔ (فتح الباری) جس قصہ کی طرف حافظ ؒ نے اشارہ کیا ہے امام غزالی ؒ نے اس کو نقل کیا ہے۔ حضر ت ابووائل ؒکہتے ہیں کہ میں اور میرا ایک ساتھی حضرت سلمانؓ کی زیارت کے لیے گئے۔ انھوں نے جو کی روٹی اور نیم کو فتہ نمک ہمارے سامنے رکھا۔ میرا ساتھی کہنے لگا کہ اگر اس کے ساتھ سَعْتَر (پودینہ کی ایک قسم ہے) ہوتا تو بڑا لذیذ ہوتا۔ حضرت سلمانؓ تشریف لے گئے اور وضو کا لوٹا رہن رکھ کر سعتر خرید کر لائے۔ جب ہم کھاچکے تومیرے ساتھی نے کہا : اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِيْ قَنَّعَنَا بِمَا رَزَقَنَا۔ (سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ماحضر پر قناعت کی توفیق عطا فرمائی) حضرت سلمانؓ نے فرمایا اگر تمہیں ماحضر پر قناعت ہوتی تو میرا لوٹا گروی نہ رکھا جاتا۔ (اِحیاء العلوم)
حاصل یہ ہے کہ میزبان سے ایسی فرمایشیں کرنا جس سے اس کو دِقّت ہو یہ بھی یُحْرِجُہُ (میزبان کو تنگی میں ڈالنے) میں داخل ہے۔ دوسرے کے گھر جا کر چُناں چُنیں کرنا، یہ چاہیے وہ چاہیے، ہرگز مناسب نہیں ہے۔ جو وہ حاضر کر رہا ہے اس کو صبر و شکر سے بشاشت کے ساتھ کھا لینا چاہیے۔ فرمایشیں کرنا بسا اوقات میزبان کی دِقّت اور تنگی کا سبب ہوتا ہے۔ البتہ اگر میزبان کے حال سے یہ اندازہ ہو کہ وہ فرمایش سے خوش ہوتا ہے۔ مثلاً: فرمایش کرنے والا کوئی محبوب ہو اور جس سے فرمایش کی جائے وہ جان نثار ہو، تو چاہے وہ فرمایش کرے۔
حضرت امام شافعی ؒ بغداد میں زعفرانی( ؒ) کے مہمان تھے اور وہ حضرت امام ؒ کی خاطر میں روزانہ اپنی باندی کو ایک پرچہ لکھا کرتا تھا جس میںاس وقت کے کھانے کی تفصیل ہوتی تھی۔ حضرت امام شافعی ؒ نے ایک وقت باندی سے پرچہ لے کر دیکھا اور اس میں اپنے قلم سے ایک چیز کا اضافہ فرما دیا۔ دستر خوان پر جب زعفرانی( ؒ) نے وہ چیز دیکھی تو باندی پر اعتراض کیا کہ میں نے اس کے پکانے کو نہیں لکھا تھا۔ وہ پرچہ لے کر آقا کے پاس آئی اور پرچہ دکھا کر کہا کہ یہ چیز حضرتِ امام ؒ نے خود اپنے قلم سے اضافہ کی تھی۔ زعفرانی( ؒ) نے جب اس کو دیکھا اور حضرت کے قلم سے اس میں اضافہ پر نظر پڑی تو خوشی سے باغ باغ ہوگیا اور اس خوشی میں اس باندی کو آزاد کر دیا۔ (اِحیاء العلوم) اگر ایسا کوئی مہمان ہو اور ایسا میزبان ہو تو یقینًا فرمایش بھی لطف کی چیز ہے۔
۲۳۔ عَنْ أَبِيْ سَعِیْدٍ ؓ أَنَّہ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺیَقُوْلُ: لَا تُصَاحِبْ إِلاَّ مُؤْمِنًا وَلاََ یَاْکُلْ طَعَامَکَ إِلَّا تَقِيٌّ۔
حضورِ اقدس ﷺ کا پاک ارشاد ہے کہ مسلمان کے علاوہ کسی کے ساتھ مُصاحبت اور ہم نشنیی نہ رکھ، اور تیرا کھانا غیرِ متقی نہ کھائے۔
اس حدیثِ پاک میں حضو رِ اقدسﷺ نے دو آداب ارشاد فرمائے۔ اول یہ کہ ہم نشینی اور نشست و برخاست غیر مسلم کے ساتھ نہ رکھ۔ اگر اس سے کامل مسلمان مراد ہے تب تو مطلب یہ ہے کہ فاسق فاجر لوگوں کے ساتھ مجالست اختیار نہ کر۔ دوسرے جملہ میں چوںکہ متقی کا ذکر ہے اس سے اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے، نیز اس سے بھی تائید ہوتی ہے کہ ایک حدیث میں حضورﷺ کا ارشاد ہے کہ نہ داخل ہوں تیرے گھر میں مگر متقی لوگ۔ (کنزالعمال)اور اگر اس سے مطلقًا مسلمان مراد ہے تو مطلب یہ ہے کہ کافروں کے ساتھ بے ضرورت مجالست اختیار نہ کی جائے۔
اور ہر صورت میں تنبیہ مقصود ہے اچھی صحبت اختیار کرنے پر۔ اس لیے کہ آدمی جس قسم کے لوگوں میں کثرت سے نشست و برخاست رکھا کرتا ہے اسی قسم کے آثار آدمی میں پیدا ہوا کرتے ہیں۔ اسی بنا پر حضورﷺکا وہ ارشاد ہے جو ابھی گزرا کہ تیرے گھر میں متقیوں کے علاوہ داخل نہ ہوں۔ یعنی ان سے میل جول ہوگا تو ان کے اثرات پیدا ہوں گے۔ حضورﷺ کا پاک ارشاد ہے کہ صالح ہم نشین کی مثال مشک بیچنے والے کی ہے کہ اگر اس کے پاس بیٹھا جائے تو وہ تجھے تھوڑا سا مشک کا ہدیہ بھی دے دے گا، تُو اس سے خرید بھی لے گا اور دونوں باتیں نہ ہوں تو پاس بیٹھنے کی وجہ سے مشک کی خوشبو سے دماغ معّطر رہے گا۔ (اور فرحت پہنچتی رہے گی) اور برے ساتھی کی مثال لوہار کی بھٹی کے پاس بیٹھنے والے کی ہے کہ اگر اس کی بھٹی سے کوئی چنگاری اڑ کر لگ گئی تو کپڑے جلا دے گی، اور یہ بھی نہ ہو تو بدبو اور دھواں تو کہیں گیا ہی نہیں۔ (مشکاۃ المصابیح)
ایک اور حدیث میں ہے کہ آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوا کرتا ہے، پس اچھی طرح غورکرلے کہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ (مشکاۃ المصابیح) مطلب یہ ہے کہ پاس بیٹھنے کا اور صحبت کا اثر بے ارادہ رفتہ رفتہ آدمی میں سرایت کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ آدمی اس کا مذہب بھی اختیار کرلیا کرتا ہے۔ اس لیے پاس بیٹھنے والوں کی دینی حالت میں اچھی طرح سے غور کرلینا چاہیے۔ بددینوں کے پاس کثرت سے بیٹھنے سے بددینی آدمی میں پیدا ہوا کرتی ہے۔ روز مرہ کاتجربہ ہے کہ شراب پینے والوں کے، شطرنج کھیلنے والوں کے پاس تھوڑے دن کثرت سے اٹھنا بیٹھنا ہو تو یہ مرض آدمی میں لگ جاتے ہیں۔
ایک اور حدیث میں ہے کہ حضورِ اقدسﷺ نے حضرت ابورَزِینؓ سے فرمایا کہ میں تجھے ایسی چیز بتائوں جس سے اس چیز پر قدرت ہوجائے جو دارَین کی خیر کا سبب ہو؟ اللہ کاذکر کرنے والوں کی مجلس اختیار کر،اور جب تو تنہا ہوا کرے تو جس قدر بھی تو کرسکے اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو حرکت دیتا رہا کر، اور اللہ کے واسطے دوستی کر اور اسی کے لیے دشمنی کر۔ (مشکاۃ المصابیح) یعنی جس سے دوستی یا دشمنی ہو وہ اللہ ہی کی رضا کے واسطے ہو ، اپنے نفس کے واسطے نہ ہو۔
امام غزالی ؒ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی مصاحبت اختیار کرے اس میں پانچ چیزیں ہونا چاہییں۔ اول صاحب عقل ہو۔ اس لیے کہ عقل اصل راس ُالمال ہے، بے وقوف کی مصاحبت میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا مآلِ کار وحشت اور قطع رحمی ہے۔ حضرت سفیان ثوری ؒ سے تو یہ بھی نقل کیا گیا کہ احمق کی صورت کو دیکھنا بھی خطا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہوں کہ جب آدمی کے اخلاق خراب ہوں تو وہ عقل پر بسا اوقات غالب آجاتے ہیں۔ ایک آدمی سمجھ دار ہے، با ت کو خوب سمجھتا ہے، لیکن غصہ، شہوت ،بخل وغیرہ اس کو اکثر عقل کا کام نہیں کرنے دیتے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ فاسق نہ ہو۔اس لیے کہ جو شخص اللہ سے بھی نہ ڈرتا ہو اس کی دوستی کا کوئی اعتبار نہیں، نہ معلوم کس جگہ کس مصیبت میں پھنسا دے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ بدعتی نہ ہو کہ اس کے تعلقات سے بدعت کے ساتھ متاثر ہو جانے کا اندیشہ ہے اور اس کی نحوست کے متعدی ہونے کا خوف ہے۔ بدعتی اس کا مستحق ہے کہ اس سے تعلقات اگر ہوں تو منقطع کرلیے جائیں، نہ یہ کہ تعلقات پیدا کیے جائیں۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ وہ دنیا کمانے پر حریص نہ ہوکہ اس کی صحبت سمِ قاتل ہے۔ اس لیے کہ طبیعت تشبُّہ اور اِقتدا پر مجبور ہوا کرتی ہے اور مخفی طور پر دوسرے کے اثرات لیا کرتی ہے۔ (اِحیاء العلوم)
حضرت امام باقر ؒ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد حضرت زین العابدین ؒ نے وصیت فرمائی ہے کہ پانچ آدمیوں کے ساتھ نہ رہنا، ان سے بات بھی نہ کرنا، حتیٰ کہ راستہ چلتے ہوئے ان کے ساتھ راستہ بھی نہ چلنا۔
۱۔ فاسق شخص کہ وہ تجھے ایک لقمہ بلکہ ایک لقمہ سے کم میں بھی فروخت کر دے گا۔ میں نے پوچھا کہ ایک لقمہ سے کم میں فروخت کرنے کا کیا مطلب؟ فرمایا کہ ایک لقمہ کی امید پر وہ تجھے فروخت کر دے پھر اس کو وہ لقمہ بھی جس کی امید تھی نہ ملے۔ (محض امید پر فروخت کردے) ۲۔ بخیل کے پاس نہ جائیو کہ وہ تجھ سے ایسے وقت میں تعلق توڑ دے گا جب تو اس کا سخت محتاج ہو۔ ۳۔ جھوٹے کے پاس نہ جائیو کہ وہ بالُو (دھوکہ) کی طرح سے قریب کو دُور اور دُور کو قریب ظاہر کرے گا۔ ۴۔ احمق کے پاس کو نہ گزرنا کہ وہ تجھے نفع پہنچانا چاہے گا اور نقصان پہنچا دے گا۔ ۵۔ قطع رحمی کرنے والے کے پاس کونہ گزریو کہ میں نے اس پر قرآنِ پاک میں تین جگہ لعنت پائی ہے۔ (روض الریاحین)
اثرات کا لینا آدمیوں ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ جس چیز کے ساتھ آدمی کا تلبُّس زیادہ ہوا کرتا ہے اس کے اثرات مخفی طور پر آدمی کے ا ندر آجایا کرتے ہیں۔ حضورِاقدسﷺ سے نقل کیا گیا کہ بکریوں والوں میں مسکنت ہوتی ہے اور فخر و تکبر گھوڑے والوں میں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ ان دونوں جانوروں میں یہ صفات پائی جاتی ہے۔ اونٹ اور بیل والوں میں شدت او ر سخت دلی بھی وارد ہوئی ہے۔ متعدد روایات میں چیتے کی کھال پر سواری کی ممانعت آئی ہے۔ علماء نے من جملہ دوسری وجوہ کے اس کی ایک وجہ یہ بھی فرمائی ہے کہ مجالست کی وجہ سے اس میں درندگی کی خصلت پیدا ہوتی ہے۔ (کوکب)
دوسرا ادب حدیثِ بالا میں یہ ہے کہ تیرا کھانا متقی لوگ ہی کھائیں۔ یہ مضمون بھی متعدد روایات میں آیا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اپنا کھانا متقی لوگوں کو کھلائو اور اپنے احسان کا مؤمنوں کو مورِد بنائو۔ (اتحاف) علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد دعوت کا کھانا ہے حاجت کا کھانا نہیں۔ چناںچہ ایک حدیث میں ہے کہ اپنے کھانے سے اس شخص کی ضیافت کرو جس سے اللہ کی وجہ سے محبت ہو۔ (اتحاف) دفعِ حاجت کے کھانے میں حق تعالیٰ شا نہٗ نے قیدیوں کے کھلانے کی بھی مدح فرمائی ہے اور قیدی اس زمانہ کے کافر تھے۔ (مظاہرِ حق) جیسا کہ آیات کے سلسلہ میں نمبر (۳۴) پر یہ مضمون گزرچکا ہے اور احادیث کے سلسلہ میں نمبر(۱۰) پر گزر چکا ہے کہ ایک فاحشہ عورت کی محض اس وجہ سے مغفرت ہوئی کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔
اور بھی متعدد روایات میں مختلف مضامین سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ حضورِاقدسﷺ نے توقاعدہ اور ضابطہ فرما دیا کہ ہر جاندار میں اجر ہے۔ اس میں متقی غیر متقی، مسلم کافر، آدمی حیوان،سب ہی داخل ہیں۔ لہٰذا اِحتیاج اور ضرورت کے کھانے میں یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتیں، وہاں تواِحتیاج کی شدت اور قلت دیکھی جاتی ہے۔ جتنی زیادہ اِحتیاج ہو اتنا ہی زیادہ ثواب ہوگا۔ یہ کھانا دعوت اور تعلقات کا ہے۔ اس میں بھی اگر کوئی دینی مصلحت ہو، خیر کی نیت ہو توجس درجہ کی خیر اور مصلحت ہوگی اسی درجہ کا اجر ہوگا۔ البتہ اگر کوئی دینی مصلحت نہ ہو تو کھانے والا جتنا زیادہ متقی ہوگا اتنا ہی زیادہ اجر کا سبب ہوگا۔
صاحب ’’ِمظاہر‘‘ اور امام غزالی ؒنے لکھا ہے کہ متقیوں کو کھلانا اطاعت اور نیکیوں پر اِعانت ہے، اور فاسقوں کو کھلانا فسق و فجور پر اعانت ہے، اور ظاہر چیز ہے کہ متقی اور نیک آدمی میں جتنی زیادہ طاقت اور قوت آئے گی عبادت میں زیادہ مصروف ہوگا، اور فاسق فاجر میں اچھے کھانوں سے جتنی زیادہ قوت ہوگی لہو و لعب فسق و فجور میں پڑے گا، جس میں اس کی اِعانت ہوئی۔
ایک بزرگ اپنے کھانے کو فقرا صوفیہ ہی کو کھلاتے تھے۔ کسی نے عرض کیا کہ اگر آپ عام فقرا کو بھی کھلائیں تو بہتر ہو۔ انھوں نے فرمایا کہ ان لوگوں کی ساری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ جب ان کو فاقہ ہوتا ہے تو اس سے توجہ میںا ِنتشار ہوتا ہے۔ میں ایک شخص کی توجہ کو اللہ تک لگائے رکھوں یہ اس سے بہتر ہے کہ ایسے ہزار آدمیوں کی اِعانت کروں جن کی ساری توجہ دنیا کی طرف ہے ۔ حضرت جنید بغدادی ؒنے جب یہ بات سنی تو بہت پسند فرمایا۔ (اِحیاء العلوم، اتحاف)
حضرت عبداللہ بن مبارک ؒ سے ایک درزی نے دریافت کیا کہ میں ظالم بادشاہوں کے کپڑے سیتا ہوں کیا آپ کا خیال ہے کہ میں بھی ظالموں کی اِعانت کر رہا ہوں؟ انھوں نے ارشاد فرمایا نہیں! تُو اِعانت کرنے والوں میں نہیں ہے تُوتو خود ظالم ہے۔ ظالم کی اِعانت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو تیرے ہاتھ سوئی دھاگہ فروخت کریں۔ (اِحیاء العلوم)
ایک حدیث میں حضورﷺکا ارشاد وارد ہوا ہے کہ جو شخص کریم پر احسان کرتا ہے اس کو غلام بنا لیتا ہے اور جو ذلیل (لئیم) شخص پراحسان کرتا ہے اس کی دشمنی اپنی طرف کھینچتا ہے۔ (کنز العمال)ایک اور حدیث میں حضورِ اقدسﷺ کا ا رشاد وارد ہوا ہے کہ اپنا کھانا متقی لوگوں کو کھلائواور اپنا احسان مؤمنین پر کرو۔ (مشکاۃ المصابیح)
اور اس میں علاوہ بالائی مصالح کے متقی اور مؤمنین کا اِعزاز و اِکرام بھی ہے، اور یہ خود مستقل طور پر مندوب اور مامور بہٖ ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے حضورِ اقدسﷺ کے پاک ارشاد کی جس میں آپ نے فاسقوں کی دعوت قبول کرنے سے منع فرمایا ہے (مشکاۃ المصابیح) من جملہ دوسری وجوہ کے ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ فاسق کی دعوت قبول کرنے میں اس کا اِعزاز واِکرام ہے۔
۲۴۔ عَنْ أَبِيْ ھُرَیْرَۃَؓ، قَالَ: یَا رَسُوْلَ اللّٰہِ! أَيُّ الصَّدَقَۃِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: جُھْدُ الْمُقِلِّ وَأبْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ۔
حضرت ابوہریرہ ؓ نے حضورِ اقدسﷺ سے سوال کیا کہ سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ حضورﷺنے ارشاد فرمایا کہ نادار کی انتہائی کوشش۔ اور ابتدا اُس سے کرو جس کی پرورش تمہارے ذمہ ہے۔
یعنی جو شخص خود ضرورت مند ہو، فقیر ہو، نادار ہو، وہ اپنی کوشش سے اپنے کو مشقت میں ڈال کر جو صدقہ کرے وہ افضل ہے۔ حضرت بِشر ؒ فرماتے ہیں کہ تین عمل بہت سخت ہیں، یعنی ان میں ہمت کا کام ہے۔ ایک تنگدستی کی حالت میں سخاوت، دوسرے تنہائی میں تقویٰ اور اللہ کا خوف، تیسرے ایسے شخص کے سامنے حق بات کا کہنا جس سے خوف ہو یا امید ہو۔ (اتحاف) یعنی اس سے اَغراض وابستہ ہیں اور یہ اندیشہ ہے کہ وہ حق بات کہنے سے میری اَغراض پوری نہ کرے گا یا کسی قسم کی مَضرت پہنچائے گا۔ حق تعالیٰ شا نہٗ کے کلامِ پاک میں بھی اس کی طرف اشارہ گزر چکا ہے۔ جیسا کہ آیات کے سلسلہ میں نمبر (۲۸) پر گزرا کہ وہ حضرات باوجود اپنی حاجت اور فقر کے دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اور اس کے ذیل میں اس کی کچھ تفصیل بھی گزر چکی ہے۔
حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں: تین شخص حضورﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں سے ایک نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرے پاس سو دینار (اشرفیاں) تھے۔ میں نے ان میں سے دس دینار اللہ کے واسطے صدقہ کر دیے۔ دوسرے صاحب نے عرض کیا کہ میرے پاس دس دینار تھے میں نے ایک دینار صدقہ کر دیا۔ تیسرے صاحب نے عرض کیا کہ میرے پاس ایک ہی دینار تھا میں نے اس کا دسواں حصہ صدقہ کیا ہے۔ حضورﷺ نے فرمایا کہ تم تینوں کا ثواب برابر ہے۔ اس لیے کہ ہر شخص نے اپنے مال کا دسواں حصہ صدقہ کیا ہے۔
ایک اور حدیث میں اسی قسم کا ایک اور قصہ وارد ہوا ہے اس میں بھی حضورِاقدسﷺ کا یہی ارشاد جواب میں ہے کہ تم سب ثواب میں برابر ہو کہ ہر شخص نے اپنے مال کا دسواں حصہ صدقہ کر دیا۔ اس حدیث میں یہ بھی وارد ہے کہ اس کے بعد حضورِ اقدسﷺ نے یہ آیتِ شریفہ پڑھی {لِیُنْفِقْ ذُوْ سَعَۃٍ مِّنْ سَعَتِہٖ} (کنز العمال) یہ آیتِ شریفہ سورئہ طلاق کے پہلے رکوع کے ختم پر ہے۔ پوری آیتِ شریفہ کا ترجمہ یہ ہے کہ وسعت والے کو اپنی وسعت کے موافق خرچ کرنا چاہیے۔ جس کی آمدنی کم ہو اس کو چاہیے کہ اللہ نے جتنا اس کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرے۔ (یعنی امیر آدمی اپنی حیثیت کے موافق خرچ کرے اور غریب آدمی اپنی حیثیت کے موافق، کیوںکہ) خدا تعالیٰ کسی شخص کو اس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا جتنا اس کو دیا ہے۔ (اور غریب آدمی خرچ کرتا ہوا اس سے نہ ڈرے کہ پھر بالکل ہی نہیں رہے گا) خدا تعالیٰ تنگی کے بعد جلد ہی فراغت بھی دے دے گا۔
علامہ سیوطی ؒ نے ’’دُرِّمنثور‘‘ میں اس آیتِ شریفہ کے ذیل میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت کے ہم معنی دوسرے بعض صحابہ سے بھی روایات نقل کی ہیں اور ان سے بڑھ کر ایک صحیح حدیث میں حضورِ اقدسﷺ کا پاک ارشاد نقل کیا گیا کہ ایک دِرَم ایک لاکھ دِرَم سے بھی ثواب میں بڑھ جاتا ہے۔ ا س طرح کہ ایک آدمی کے پاس دو ہی دِرَم فقط ہیں، اس نے ان میں سے ایک صدقہ کر دیا۔ دوسرا شخص ایسا ہے کہ اس کے پاس بہت بڑی مقدار میں مال ہے اس نے اپنے کثیر مال میں سے ایک لاکھ دِرَم صدقہ کیے تو یہ ایک دِرَم ثوا ب میں بڑھ جائے گا۔
علامہ سیوطی ؒ نے ’’جامع صغیر‘‘ میں حضرت ابو ذر اور حضرت ابو ہریرہ ? کی روایات سے اس کو نقل کیا ہے اور صحیح کی علامت لکھی ،یہی نادار کی کوشش ہے کہ ایک شخص کے پاس صرف دو دِرَم ہیں۔ یعنی ۷؍کہ ایک دِرَم تقریبًا ۳؍ کا ہوتا ہے۔ 1 ان میں سے ایک صدقہ کر دیا۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے جس کو امام بخاری ؒ نے روایت کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضورِ اقدسﷺ جب ہم لوگوں کو صدقہ کا حکم فرمایا کرتے تھے تو ہم میں سے بعض آدمی بازار جاتے اور اپنے اوپر بوجھ لاد کر مزدوری میں ایک مُدّ (جو حنفیہ کے نزدیک ایک سیر وزن ہے اور دوسرے حضرات کے نزدیک تین پائو سے بھی کچھ کم ہے) کماتے اور اس کو صدقہ کر دیتے۔ (فتح الباری)
بعض روایات میں ہے کہ ہم میں سے بعض آدمی جن کے پاس ایک دِرَم بھی نہ ہوتا تھا بازار جاتے اور لوگوں سے اس کی خواہش کرتے کہ کوئی مزدوری پر کام کرالے اور اپنی کمر پر بوجھ لاد کر ایک مُدّمزدوری حاصل کرتے۔ راوی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جہاں تک خیال ہے خود حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے یہ اپنا ہی حال بتایا ہے۔
حضرت امام بخاری ؒ نے ا س پر یہ باب ذکر کیا ہے: بیان اس شخص کا جو اس لیے مزدوری کرے کہ اپنی کمر پر بوجھ لادلے اور پھر اس مزدوری کو صدقہ کر دے۔(فتح الباری)
آج ہم میں سے بھی کوئی اس امنگ کا آدمی ہے کہ اسٹیشن پر جاکر صرف اس لیے بوجھ اٹھائے کہ دو چار آنے جو مل جائیں گے وہ ان کو صدقہ کر دے گا؟ ان حضرات کو آخر ت کے کھانے کا ہر وقت اتنا ہی فکر رہتا تھا جتنا ہمیں دنیا کے کھانے کا ۔ ہم اس لیے مزدوری کرتے ہیں کہ آج کھانے کو کچھ نہیں، لیکن یہ اس لیے مزدوری کرتے تھے کہ آج آخرت میں جمع کرنے کو کچھ نہیں ہے۔ ابتدائے اسلام میں بعض منافق ایسے لوگوں پر طعن کرتے تھے جو مشقت اٹھا کر تھوڑا تھوڑا صدقہ کرتے تھے، حق تعالیٰ شا نہٗ نے ان پر عتاب فرمایا۔ چناںچہ ارشاد ہے:
{ اَلَّذِیْنَ یَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِیْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ فِی الصَّدَقٰتِ وَالَّذِیْنَ لَایَجِدُوْنَ اِلاَّ جُھْدَھُمْ فَیَسْخَرُوْنَ مِنْھُمْ ط سَخِرَ اللّٰہُ مِنْھُمْ ز وَلَھُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ o} ( التوبۃ : ع ۱۰)
یہ (منافق) ایسے لوگ ہیں کہ نفل صدقہ کرنے والے مسلمانوں پر صدقات کے بارہ میں طعن کرتے ہیں، اور (بالخصوص )ان لوگوں پر (اور بھی زیادہ )طعن کرتے ہیں جن کو بجز محنت اور مزدوری کے کچھ میسر نہیں ہوتا، یہ (منافق) ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان کے مذاق اڑانے کا بدلہ (اسی نوع سے ) دے گا (کہ آخرت میں ان احمقوں کا بھی اول مذاق اڑایا جائے گا) اور دکھ دینے والا عذاب تو ان کے لیے ہے ہی۔ (وہ تو ٹلتا نہیں)
مفسرین نے اس آیتِ شریفہ کے ذیل میں بہت سی روایات اس قسم کی ذکر کی ہیں کہ یہ حضرات رات بھر حمّالی کرکے مزدوری کماتے اور صدقہ کرتے، اور جو کچھ تھوڑا بہت گھر میں ہوتا وہ تو ان کی نگاہ میں صدقہ ہی کے واسطے ہوتا تھا، مجبوری کے درجہ میں کچھ خود بھی استعمال کرلیا۔
ایک مرتبہ حضرت علی ؓ کی خدمت میں ایک سائل حاضر ہوا۔ آپ نے اپنے صاحب زادہ حضرت حسن یا حضرت حسین ? سے فرمایا کہ اپنی والدہ ( حضرت فاطمہؓ) سے کہو کہ میں نے جو چھ دِرَم ہم تمہارے پاس رکھے ہیں ان میں سے ایک دے دو۔ صاحب زادے گئے اور یہ جواب لائے کہ وہ آپ نے آٹے کے لیے رکھوائے تھے۔ حضرت علی ؓ نے فرمایا کہ آدمی اپنے ایمان میںا س وقت تک سچا نہیں ہوتا جب تک کہ اپنے پاس کی موجود چیز سے اس چیز پر زیادہ اعتماد نہ ہو جو اللہ کے پاس ہے۔ اپنی والدہ سے کہو کہ وہ چھ دِرَم سب کے سب دے دو۔ حضرت فاطمہؓ نے تو یاد دہانی کے طور پر فرمایا تھا ان کو اس میں کیا تامّل ہو سکتا تھا، اس لیے حضرت فاطمہؓ نے دے دیے۔ حضرت علیؓ نے وہ سب سائل کو دے دیے۔ حضرت علیؓ اپنی اس جگہ سے اٹھے بھی نہیں تھے کہ ایک شخص اونٹ فروخت کرتا ہوا آیا۔ آپ نے اس کی قیمت پوچھی۔ اس نے ایک سو چالیس دِرَم بتائے۔ آپ نے وہ قرض خرید لیا اور قیمت کی ادائیگی کا بعد کا وعدہ کرلیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص آیا اور اونٹ کو دیکھ کر پوچھنے لگا کہ یہ کس کا ہے۔ حضرت علیؓ نے فرمایا کہ میرا ہے۔ اس نے دریافت کیا کہ فروخت کرتے ہو؟ حضرت علیؓ نے فرمایا: ہاں۔ اس نے قیمت دریافت کی، حضرت علی ؓنے دو سو دِرَم بتائے وہ خرید کر لے گیا۔ حضرت علیؓ نے ایک سو چالیس دِرَم اپنے قرض خواہ یعنی پہلے مالک کو دے کر ساٹھ دِرَم حضرت فاطمہؓ کو لا کر دے دیے۔ حضرت فاطمہؓ نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے؟ حضرت علیؓ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے نبی کے واسطے سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو شخص نیکی کرتا ہے اس کو دس گناہ بدلہ ملتا ہے۔ (کنز العمال)
یہ بھی جُہد والے کی مشقت تھی کہ کُل صرف چھ دِرَم1 کل موجود تھے جو آٹے کے لیے رکھے ہوئے تھے ۔اللہ پر کامل اعتماد کرکے ان کو خرچ فرما دیا اور دَہ دَر دنیا کا بدلہ وصول کرلیا۔ اور بھی بہت سے واقعات ان حضرات کے اللہ پر اعتمادِ کامل کرکے سب کچھ خرچ کر ڈالنے کے وارد ہوئے ہیں۔
حضرت ابوبکر صدیقؓکا قصہ غزوئہ تبوک کا مشہور معروف ہے کہ جب حضورﷺ نے صدقہ کا حکم فرمایا تو جو کچھ گھر میں تھا سب کچھ لاکر پیش کر دیا اور حضورﷺ کے دریافت فرمانے پر کہ گھر میں کیا چھوڑا عرض کیا: اللہ اور اس کے رسول کو۔ یعنی ا ن کو رضا کو۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب حضر ت ابوبکر صدیقؓ ایمان لائے تو ان کے پاس چالیس ہزار اشرفیاں تھیں۔ (تاریخ الخلفاء)
محمد بن عبّاد مہلّبی ؒ کہتے ہیں کہ میرے والد مامون رشید بادشاہ کے پاس گئے۔ بادشاہ نے ایک لاکھ دِرَم ہدیہ دیا۔ والد صاحب جب وہاں سے اٹھ کر آئے تو سب کے سب صدقہ کردیے۔ مامون کو اس کی اطلاع ہوگئی۔ جب دوبارہ والد صاحب کی ملاقات ہوئی تومامون نے ناراضی کا اظہار کیا۔ والد صاحب نے کہا: اے امیر المؤمنین! موجود کا روکنا معبود کے ساتھ بدگمانی ہے۔ (اِحیاء العلوم) یعنی جوچیز موجود ہے اس کو خرچ نہ کرنا اسی خوف سے تو ہوتا ہے کہ یہ نہ رہے گی تو کہاں سے آئے گی؟ تو گویا جس مالک نے اس وقت دیا ہے اس کو دوبارہ دینا مشکل پڑ جائے گا۔
بہت سے واقعات اَسلاف واَکابر کے ایسے گزرے ہیں کہ ناداری کی حالت میں بھی جو کچھ تھا سب دے دیا، لیکن ان سب روایات اور واقعات کے خلاف احادیث میں ایک مضمون اور بھی آیا ہے، اور وہ حضورِ اقدسﷺ کا پاک اور مشہور ارشاد: خَیْرُ الصَّدَقَۃِ مَا کَانَ عَنْ ظَھْرِ غِنیًہے۔ بہترین صدقہ وہی ہے جو غنا سے ہو۔ یہ مضمون بھی متعدد روایات میں وارد ہوا ہے۔
’’ابو داؤد شریف‘‘ میں ایک قصہ وارد ہوا ہے۔ حضر ت جابرؓ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضورِ اقدسﷺ کی خدمت میں حاضر تھے۔ ایک شخص حاضر ہوئے اور ایک بَیضہ (انڈہ) کے بقدر سونا پیش کرکے عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ مجھے ایک معدن سے مل گیا ہے اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضورﷺ نے اس جانب سے اِعراض فرما لیا۔ وہ صاحب دوسری جانب سے حاضر ہوئے اور یہی درخواست مکرَّر پیش کی۔ حضورﷺ نے اس طرف سے بھی منہ پھیر لیا۔ اسی طرح متعدد مرتبہ ہوا۔ حضورﷺ نے اس ڈلی کو لے کر ایسے زور سے پھینکا کہ اگر وہ ان کے لگ جاتی تو زخمی کر دیتی۔ اس کے بعد حضورﷺ نے فرمایا: بعض لوگ اپنا سارا مال صدقہ میں پیش کر دیتے ہیں پھر وہ لوگوں کے سامنے سوال کا ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ بہترین صدقہ وہ ہے جو غنیٰ سے ہو۔
حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں حاضر ہوئے۔ حضورِاقدسﷺ نے (ان کی بدحالی دیکھ کر) لوگوں سے کپڑا صدقہ کرنے کی ترغیب دی۔ لوگوں نے کچھ کپڑے پیش کیے جن میں سے دو کپڑے حضورﷺ نے ان کو بھی مرحمت فرمائے جو اس وقت مسجد میں داخل ہوئے تھے۔ اس کے بعد دوسرے موقعہ پر حضورﷺ نے پھر لوگوں کو صدقہ کی ترغیب دی تو انھوں نے بھی اپنے دو کپڑوں میں سے ایک کپڑا صدقہ کر دیا۔ حضورﷺ نے ان کو تنبیہ فرمائی اور ان کا کپڑا واپس فرما دیا۔ (ابوداود)
ایک اور حدیث میں اس قصہ میں حضورﷺ کا یہ ارشاد وارد ہوا ہے کہ یہ صاحب نہایت بری ہیئت سے مسجد میں آئے تھے، مجھے یہ امید تھی کہ تم ان کی حالت دیکھ کر خود ہی خیال کرو گے، مگرتم نے خیال نہ کیا تو مجھے کہنا پڑا کہ صدقہ لائو۔ تم صدقہ لائے اور ان کو دو کپڑے دے دیے۔ پھر میں نے دوسری مرتبہ جب صدقہ کی ترغیب دی تو یہ بھی اپنے دو کپڑوں میں سے ایک صدقہ کرنے لگے، لو اپنا کپڑا واپس لو۔ (کنز العمال)
ایک اور حدیث میں حضورِ اقدسﷺ کاارشاد وارد ہوا ہے کہ بعض آدمی اپنا سارا مال صدقہ کر دیتے ہیں پھر بیٹھ کر لوگوں کے ہاتھوں کو دیکھتے ہیں۔ بہترین صدقہ وہ ہے جو غنیٰ سے ہو۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ بغیر غنیٰ کے صدقہ ہے ہی نہیں۔ (کنز العمال)
یہ روایات بظاہر پہلی روایات کے خلاف ہیں گو حقیقت میں کچھ خلاف نہیں ہے۔ اس لیے کہ ان روایات میں ممانعت کی وجہ کی طرف حضورﷺ نے خود ہی اشارہ فرما دیا کہ سارا مال صدقہ کرکے پھر لوگوں کے ہاتھوں کو تکتے ہیں۔ ایسے آدمیوں کے لیے یقینًا تمام مال صدقہ کرنا مناسب نہیں بلکہ نہایت بے جاہے، لیکن جو حضرات ایسے ہیں کہ ان کو اپنے پاس جو مال موجود ہو، اس سے زیادہ اعتماد اس مال پر ہو جو اللہ کے قبضہ میں ہے جیسا کہ حضرت علی ؓ کے قصہ میں ابھی گزرا اور حضرت ابوبکر صدیقؓ کے احوال تو اس سے بھی بالاتر ہیں، ایسے حضرات کو سارا مال صدقہ کر دینے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ البتہ اس کی کوشش ضرور کرتے رہنا چاہیے کہ اپنا حال بھی ان حضرات جیسا بن جائے، اور دنیا سے ایسی بے رغبتی اور حق تعالیٰ شا نہٗ پر ایسا ہی اعتماد پیدا ہو جائے جیسا ان حضرات کو تھا۔ اور جب آدمی کسی کام کی کوشش کرتا ہے تو حق تعالیٰ شا نہٗ وہ چیز عطا فرماتے ہی ہیں۔ مَنْ جَدَّ وَجَدَ ضرب المثل ہے کہ جو کوشش کرتا ہے وہ پالیتا ہے۔
ایک بزرگ سے کسی نے دریافت کیا کہ کتنے مال میں کتنی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ انھوں نے فرمایا کہ عوام کے لیے دو سو دِرَم میں پانچ دِرَم یعنی چالیسواں حصہ شریعت کا حکم ہے، لیکن ہم لوگوں پر سارا مال صدقہ کر دینا واجب ہے۔ (اِحیاء العلوم: ج ) اسی ذیل میں حضورﷺ کے وہ ارشادات ہیں جو احادیث کے سلسلہ میں نمبر (۱) پر گزرے کہ اگر اُحد کا پہاڑ سارے کا سارا سونا بن جائے تو مجھے یہ گوارا نہیں کہ اس میں سے ایک دِرَم بھی باقی رکھوں، بجز اس کے جو قرض کی ادائیگی کے لیے ہو۔ اسی بنا پرحضورِ اقدس ﷺ عصر کی نماز کے بعد نہایت عجلت سے مکان تشریف لے گئے اور سونے کا ٹکڑا جو گھر میں اتفاق سے رہ گیا تھا اس کو صدقہ کا حکم فرما کر واپس تشریف لائے، اور چند داموں کی موجودگی کی وجہ سے اپنی علالت میں بے چین ہوگئے جیسا کہ سلسلۂ احادیث میں نمبر (۴ )پر گزرا۔ حضرت امام بخاری ؒ نے اپنی ’’صحیح بخاری شریف‘‘ میںفرمایا کہ صدقہ بغیر غنیٰ کے نہیں ہے اور جو شخص ایسی حالت میں صدقہ کرے کہ وہ خود محتاج ہو یا اس کے اہل و عیال محتاج ہوں یا اس پر قرض ہو تو قرض کا ادا کرنا مقدم ہے، ایسے شخص کا صدقہ اس پر لوٹا دیاجائے گا۔ البتہ اگر کوئی شخص صبرکرنے میں معروف ہو اور اپنے نفس پر باوجود اپنی اِحتیاج کے ترجیح دے جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیقؓ کا فعل تھا یا انصار نے مہاجرین کو اپنے اوپر ترجیح دی۔ (تو اس میں مضائقہ نہیں)
علامہ طبری ؒکہتے ہیں: جمہور
علماء کا یہ مذہب ہے کہ جو شخص اپنا سارا مال صدقہ کر دے بشرطے کہ اس پر قرض نہ ہو اور تنگی کی اس میں برداشت ہو اور اس کے عیال نہ ہوں یا اگر ہوں تو وہ بھی اس کی طرح سے صابر ہوں، توسارا مال صدقہ کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں، اور ان میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے تو سارا مال صدقہ کرنا مکروہ ہے۔ (فتح الباری)
ہمارے حضرت حکیم الامت شاہ ولی اللہ صاحب نوّر اللہ مرقدہٗ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضورﷺ کے پاک ارشاد ’’بہترین صدقہ وہ ہے جو غنیٰ سے ہو‘‘ میںغنیٰ سے مراد دل کا غنیٰ ہے۔ (حجۃ اللہ البالغۃ) اس صورت میں یہ احادیث پہلی احادیث کے خلاف بھی نہیں ہیں۔ خودحضورِ اقدسﷺ کا پاک ارشاد بھی احادیث میں آیا ہے کہ غنیٰ مال کی کثرت سے نہیں ہوتا بلکہ اصل غنیٰ دل کا ہوتا ہے۔ (مشکاۃ المصابیح)
اوپر جو قصہ سونے کی ڈلی کا گزرا اس میں بھی اشارۃً یہ مضمون ملتا ہے کہ ان صاحب کا بار بار یہ عرض کرنا کہ یہ سارا صدقہ ہے اور میرے پاس اس کے سوا کچھ نہیں ہے، اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ دل کو اس سے وابستگی ہے۔
صاحبِ ’’مظاہر‘‘ فرماتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ صدقہ غنا سے دیا جائے چاہے غنائے نفس ہو۔ یعنی اللہ پر اعتمادِ کامل ہو جیسا کہ ابوبکر صدیقؓ نے جب تمام مال اللہ کے لیے دے دیا اور حضورﷺ کے اس ارشاد پر کہ اپنے عیال کے لیے کیا چھوڑا؟ انھوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسولﷺ، تو حضور ﷺنے ان کی تعریف فرمائی۔ اور یہ درجہ حاصل نہ ہو تو پھر مال کا غنیٰ باقی رہے۔
حاصل یہ ہے کہ توکُّلِ کامل ہو تو جو چاہے خرچ کر دے اور یہ کامل نہ ہو تو اہل و عیال کی رعایت کو مقدم کرے۔ (مظاہرِ حق) مگر اپنے دل کو اپنی اس کوتاہی پر تنبیہ کرتا رہے اور غیرت دلاتا رہے کہ تجھے اس ناپاک دنیا پر جتنا اعتماد ہے اللہ پر اس کا آدھا تہائی بھی نہیں ہے، ان شاء اللہ اس کے باربار تنبیہ سے ضروراثر ہوگا۔ کاش! حق تعالیٰ شا نہٗ ان اَکابر کے توکُّل اور اعتماد کا کچھ حصہ اس کمینہ کو بھی عطا فرما دیتا ۔
۲۵۔ عَنْ عَائِشَۃَؓ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِﷺ: إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَۃُ مِنْ طَعَامِ بَیْتِھَا غَیْرَ مُفْسِدَۃٍ کَانَ لَھَا أَجْرُھَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِھَا أَجْرُہُ
حضورِاقدسﷺ کا ارشاد ہے کہ جب عورت اپنے گھر کے کھانے میں سے ایسی طرح صدقہ کرے کہ (اِسراف وغیرہ سے) اس کو خراب نہ کرے ، تو اس کو خرچ کرنے کا
بِمَا کَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذٰلِکَ، لَایَنْقُصُ بَعْضُھُمْ أَجَْرَ بَعْضٍ شَیْئًا ۔
متفق علیہ، کذا في مشکاۃ المصابیح۔ثواب ہے اور خداوند کو اس لیے ثواب ہے کہ اس نے کمایا تھا اور کھانے کا انتظام کرنے والے کو (مرد ہو یا عورت) ایسا ہی
ثواب ہے، اور ان تینوں میں سے ایک کے ثواب کی وجہ سے دوسرے کے ثواب میں کمی نہ ہوگی۔
فائدہ:
اس حدیث شریف میں دو مضمون وارد ہوئے ہیں، ایک بیوی کے خرچ کرنے کے متعلق ہے، دوسرا سامان کے محافظ خزانچی اور منتظم کے متعلق ہے، اور دونوں مضامین میں روایات بہ کثرت وارد ہوئی ہیں۔ شیخین کی ایک اور روایت میں حضور ﷺکا ارشاد ہوا ہے کہ جب عورت خاوند کی کمائی میں سے اس کے بغیر حکم کے خرچ کرے تو اس عورت کو آدھا ثواب ہے۔ (مشکاۃ المصابیح)
حضرت سعدؓ فرماتے ہیں کہ جب حضورِ اقدسﷺ نے عورتوں کی جماعت کو بیعت کیا توایک عورت کھڑی ہوئیں جو بڑے قد کی تھیں ایسا معلوم ہوتا تھا جیسا کہ قبیلۂ مُضَر کی ہوں کہ ان کے قد لانبے ہوتے ہوں گے او ر عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم عورتیں اپنے والدوں پر بھی بوجھ ہیں، اپنی اولاد پر بھی اور اپنے خاوندوں پربھی بوجھ ہیں، ہمیں ان کے مال سے کیا چیز لینے کا حق ہے؟ حضورﷺ نے فرمایا: تروتازہ چیزیں (جن کے روکنے میں خراب ہونے کا اندیشہ ہو) کھا بھی سکتی ہو اور دوسروں کو دے بھی سکتی ہو۔ (مشکاۃ المصابیح) ایک اور حدیث میںحضورِاقدسﷺ کا پاک ارشاد وارد ہوا ہے کہ اللہ روٹی کے ایک لقمہ اور کھجور کی ایک مٹھی کی وجہ سے تین آدمیوں کو جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ ایک گھر کے مالک کو یعنی خاوند کو، دوسرے بیوی کو جس نے یہ کھانا پکایا، تیسرے اس خادم کو جو دروازہ تک مسکین کو دے کر آیا۔ (کنز العمال)
حضرت عائشہؓ کی ہمشیرہ حضرت اسماءؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، بجز اس کے جو (میرے خاوند) حضرت زبیر مجھے دے دیں۔ کیا میں اس میں سے خرچ کرلیا کروں؟ حضورِ ﷺ نے فرمایا: خوب خرچ کیا کرو، باندھ کر نہ رکھو کہ تم پر بھی بندش کر دی جائے گی۔ (کنز العمال) یہ روایت اور اس کے ہم معنی کئی روایتیں ابھی گزری ہیں۔
ایک اور روایت میں حضورﷺ کا ارشاد ہے کہ جب عورت خاوند کی کمائی میں سے اس کے بغیر حکم کے خرچ کرے تو خاوند کو آدھا ثواب ہے۔ (عینی عن مسلم) ابھی ایک روایت میں اس کا عکس گزر چکا کہ ایسی صورت میں عورت کے لیے آدھا ثواب ہے، لیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ خاوند کی کمائی سے خرچ کرنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ خاوند نے کما کر مال کا کچھ حصہ عورت کو بالکل دے دیا اس کو مالک بنا دیا۔ ایسے مال میں سے اگر عورت خرچ کرے تو اس کو پورا ثواب اورخاوند کو نصف ثواب۔ ظاہر ہے کہ خاوند تو بہرحال عورت کو دے چکا ہے، اب اگر وہ خرچ کرتی ہے تو حقیقت میں خاوند کے مال میں سے خرچ نہیں کرتی بلکہ اپنے مال میں سے خرچ کرتی ہے، لیکن کمائی چوںکہ خاوند کی ہے، اس لیے اس کوبھی اللہ کے لطف و کرم سے اس کی کمائی کی وجہ سے اس کے صدقہ کرنے کا آدھا ثواب ہے اور بیوی کو دے دینے کا مستقل ثواب پہلے علیحدہ ہو چکا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ خاوند نے کمانے کے بعد عورت کو مالک نہیں بنایا، بلکہ گھرکے اخراجات کے لیے اس کو دیا ہے۔ اس مال میں سے صدقہ کرنے کا خاوند کو پورا ثواب ہو کہ وہ اصل مالک ہے اور عورت کو آدھا کہ اخراجات میں تنگی تو اس کو بھی پیش آئے گی۔ ان کے علاوہ اور بھی متعدد روایات میں مختلف عنوانات سے عورتوں کو ترغیب دی گئی کہ وہ کھانے کی چیزوں میں سے اللہ کے راستہ میں خرچ کیا کریں ذرا ذرا سی چیزوں میں یہ بہانہ تلاش نہ کیا کریں کہ خاوند کی اجازت تو لی نہیں، لیکن ان سب روایات کے خلاف بعض روایات میں اس کی ممانعت بھی وارد ہوئی ہے۔
حضرت ابوامامہ ؓ فرماتے ہیں کہ حضورِ اقدسﷺ نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں من جملہ اور ارشادات کے یہ بھی فرمایا کہ کوئی عورت خاوند کے گھر سے (یعنی اس کے مال میں سے) بغیر اس کی اجازت کے خرچ نہ کرے۔ کسی نے دریافت کیا: حضور(ﷺ)! کھانا بھی بغیر اجازت خرچ نہ کرے؟ حضورﷺ نے فرمایا کہ کھانا توبہترین مال ہے۔ (الترغیب والترہیب عن الترمذي) یعنی اس کو بھی بغیر اجازت خرچ نہ کرے۔
اس روایت کو پہلی روا یت سے کوئی حقیقت میں مخالفت نہیں ہے۔ پہلی سب روایات عام حالات اور معروف عادات کی بنا پر ہیں۔ گھروں کا عام عرف سب جگہ یہی ہے اور یہی ہوتا ہے کہ جو چیزیں سامان یا روپیہ پیسہ گھر میں اخراجات کے واسطے دے دیا جاتا ہے، اس میں خاوندوں کو اس سے خلاف نہیں ہوتا کہ عورتیں اس میں سے کچھ صدقہ کر دیں یا غربا کو کچھ کھانے کودے دیں، بلکہ خاوندوں کا ایسی چیزوں میں کُنج کائو اور پوچھنا، تحقیق کرنا، کنجوسی اور چھچورپن شمار ہوتا ہے، لیکن اس عرفِ عام کے باوجود اگر کوئی بخیل اس کی اجازت نہ دے کہ اس میں سے کسی کو دیا جائے تو پھر عورت کو جائز نہیں کہ اس کے مال میں سے کچھ صدقہ کرے یا ہدیہ دے۔ البتہ اپنے مال میں سے جو چاہے خرچ کرے۔
ایک شخص نے حضورﷺ سے عرض کیا: یا رسول اللہ! میری بیوی میرے مال میں سے میری بغیر اجازت خرچ کرتی ہے۔ حضورﷺ نے فرمایا: تم دونوں کو اس کاثواب ہوگا۔ انھوں نے عرض کیا کہ میں اس کو منع کر دیتا ہوں۔ حضور ﷺ نے فرمایا تجھے تیرے بخل کا بدلہ ملے گا، اس کو اس کے احسان کا اجر ہوگا۔ (کنز العمال)
معلوم ہوا کہ خاوندوں کا ایسی معمولی چیز سے روکنا بخل ہے او ر اس کے روکنے کے بعد اس کے مال میں سے عورت کو خرچ کرنا جائز نہیں۔ البتہ عورت کا اگر دل خرچ کرنے کوچاہتا ہے اور خاوند کی مجبوری سے رُکی ہوئی ہے تو اس کو اس کی نیت کی وجہ سے صدقہ کاثواب ملتا ہی رہے گا۔
علامہ عینی ؒ فرماتے ہیں حقیقت میں ان چیزوں میں ہر شہر کا عرف اور عادت مختلف ہوتی ہے، اور خاوندوں کے احوال بھی مختلف ہوتے ہیں۔ بعض پسند کرتے ہیں اور بعض پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح جو چیز خرچ کی جائے اس کے اعتبار سے بھی مختلف احوال ہوتے ہیں۔ ایک تو معمولی چیز قابلِ تسامح ہوتی ہے اور کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کی خاوند کو اہمیت ہو۔ اسی طرح سے کوئی تو ایسی چیز ہوتی ہے جس کے رکھنے میں اس کے خراب ہو جانے کااندیشہ ہو اور کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کے روکنے میں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ حافظ ابنِ حجر ؒ نے نقل کیا ہے کہ یہ شرط تو متفق علیہ ہے کہ وہ عورت خرچ کرنے میں فساد کرنے والی نہ ہو۔
بعض علماء نے کہا ہے کہ خرچ کرنے کی ترغیبیں حجاز کے عرف کے موافق وارد ہوئی ہیں کہ وہاں بیویوں کو اس قسم کے تصرفات کی عام اجازت ہوتی تھی کہ وہ مساکین کو، مہمانوں کو، پڑوس کی عورتوں کو، سوال کر نے والوں کو کھانے وغیرہ کی چیزیں دے دیں۔ حضورِاقدسﷺ کا مقصد ان روایات سے اپنی امت کو ترغیب دینا ہے کہ عرب کی یہ نیک خصلت اختیار کریں۔ (مظاہرِ حق)
چناںچہ ہمارے دیار میں بھی بہت سے گھروں میں یہ عرف ہے کہ اگر سائل یا کسی عزیز یا ضروت مند کو، بھوکے کو، کھانے پینے کی چیزیں دے دی جائیں تو خاوندوں کے نزدیک یہ چیز نہ ان سے قابلِ اجازت ہے، نہ یہ ان کے لیے موجب ِتکدُّر ہوتا ہے۔
دوسرا مضمون حدیثِ بالا میں محافظ اور خزانچی کے متعلق وارد ہوا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اصل مالک کسی شخص کو ہدیہ دینے کی ، صدقہ کرنے کی خواہش رکھتا ہے، مگر یہ خزانچی اور محافظ کارکن اس میں رخنہ پیدا کیا کرتے ہیں۔ بالخصوص امرا اور سلاطین کے یہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مالک کی طرف سے صدقات کے پروانے جاری ہوتے ہیں اور یہ میر منشی ہمیشہ عدمِ گنجایش کا عذر کھڑا کرتے ہیں۔ اس لیے حضورِ اقدسﷺ نے متعدد روایات میں اس کی ترغیب دی ہے کہ یہ کارکن حضرات اگر نہایت طیب ِخاطر اور خندہ پیشانی سے مالک کے حکم کی تعمیل کریں، تو ان کو محض ذریعہ اور واسطہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے فضل و انعام سے مستقل ثواب ملے، جیسا کہ اوپر کے مضمون میں متعدد روایات اس کی گزر چکی ہیں۔
ایک حدیث میں ہے کہ اگر مسلمان خزانچی امانت دار مالک کے حکم کی تعمیل پوری پوری خندہ پیشانی اور خوش دلی کے ساتھ کرے، اور جتنا دینے کا اس کو حکم ہے اتنا ہی دے دے تو وہ بھی صدقہ کرنے والوں میں ہے ۔ (مشکاۃ المصابیح)
ایک حدیث میں ہے کہ اگر صدقہ (بالفرض) سات کروڑ آدمیوں کے ہاتھ میں سے نکل کر آئے تو آخر والے کو بھی ایسا ہی ثواب ہوگا جیسا کہ اوّل والے کو۔ (کنز العمال) یعنی مثلاً: کسی بادشاہ نے صدقہ کا حکم دیا اور اس کے عملہ کے اتنے آدمیوں کو اس میں واسطہ بننا پڑا تو سب کو ثواب ہوگا۔ یعنی اجر و ثواب کے اعتبار سے وہ بھی سب ایسے ہی ہیں جیسا کہ صدقہ کرنے والا ثواب کا مستحق ہے،گو دونوں کے ثواب میں فرقِ مراتب ہو۔ اور فرقِ مراتب کے لیے یہ ضروری نہیں کہ مالک ہی کا ثواب زیادہ ہو۔ کہیں مالک کا ثواب زیادہ ہوگا، مثلًا: سو روپیہ ملازم کو یا خزانچی کو حکم کرے کہ فلاں شخص کو جو دروازہ پر یا اپنے پاس موجود ہے دے دے، اس صورت میں یقینًا مالک کو ثواب زیادہ ہوگا۔ اور ایک انار کسی کو دے کہ فلاں محلہ میں جو بیمار ہے اس کو دے آئو کہ اتنی دور جانا انار کی قیمت سے بھی مشقت کے اعتبار سے بڑھ جائے، تو اس صورت میں اس واسطہ کا ثواب اصل مالک سے بھی بڑھ جائے گا۔ (عینی)
اسی طرح سے اس خازن کو مال کی تحصیل میں مشقت زیادہ اٹھانی پڑتی ہواور مالک کو بے محنت مفت میں مل جائے، تو ایسے مال کے صدقہ کرنے میں یقینًا خازن کا ثواب زیادہ ہو جائے گا کہ اَلْأَجْرُ عَلَی قَدْرِ النَّصَبِ۔ ’’ثواب مشقت کی بقدر ہوا کرتا ہے۔ ‘‘ یہ شریعتِ مطہرہ کا مستقل ضابطہ ہے، لیکن جیساکہ بیوی کے لیے بغیر اِذنِ خاوند کے تصر ف کرنے کا فی الجملہ حق ہے، خازن کے لیے یہ جائز نہیں کہ بغیر اِذنِ مالک کے کوئی تصرف اس کے مال میں کرے۔ البتہ اگر مالک کی طرف سے تصرف کی اجازت ہو تو مضائقہ نہیں۔
۲۶۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ?مَرْفُوْعًا فِيْ حَدِیْثٍ لَفْظُہُ: کُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَۃٌ، وَالدَّالُ عَلَی الْخَیْرِ کَفَاعِلِہٖ، وَاللّٰہُ یُحِبُّ إِغَاثَۃَ اللَّھْفَانِ۔
حضورِ اقدسﷺ کا ارشاد ہے کہ ہر بھلائی صدقہ ہے اورکسی کارِ خیر پر دوسرے کو ترغیب دینے کا ثواب ایسا ہی ہے جیسا کہ خود کرنے کا ثواب ہے اور اللہ مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کو محبوب رکھتا ہے۔
کذا في المقاصد الحسنۃ وبسط في تخریجہ وطرقہ، وذکر السیوطي في الجامع الصغیر حدیث ’’الدال علی الخیرکفاعلہ‘‘ من روایۃ ابن مسعود وأبي مسعود وسھل بن سعد وبریدۃ وأنس۔
فائدہ:
اس حدیث پاک میں تین مضمون ہیں۔ اول یہ کہ ہر بھلائی صدقہ ہے۔ یعنی صدقہ کے لیے مال ہی دینا ضروری نہیں ہے اور صدقہ اسی میں منحصر نہیں، بلکہ جو بھلائی کسی کے ساتھ کی جائے وہ ثواب کے اعتبار سے صدقہ ہے۔
ایک روایت میں ہے کہ آدمی کے اندر تین سو ساٹھ جوڑ ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر جوڑ کی طرف سے روزانہ ایک صدقہ کیا کرے۔ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ ! اس کی طاقت کس کو ہے؟ (کہ تین سو ساٹھ صدقہ روزانہ کیا کرے) حضورﷺ نے فرمایا: مسجد میں تھوک پڑا ہو اس کو ہٹا دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ راستہ میں کوئی تکلیف دینے والی چیز پڑی ہو اس کو ہٹا دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور کچھ نہ ملے تو چاشت کی دو رکعت نفل سب کے قائم مقام ہوجاتی ہیں۔ (مشکاۃ المصابیح) اس لیے کہ نماز میںہر جوڑ کو اللہ کی عبادت میں حرکت کرنا پڑتی ہے۔
ایک حدیث میں ہے کہ روزانہ جب آفتاب طلوع ہوتا ہے تو آدمی پر ہر جوڑ کے بدلہ میں ایک صدقہ ہے۔ دو آدمیوں کے درمیان انصاف کردو یہ بھی صدقہ ہے، کسی شخص کی سواری پر سوار ہونے میں مدد کر دو یہ بھی صدقہ ہے، اس کا سامان اٹھاکر دے دو یہ بھی صدقہ ہے، کلمۂ طیبہ (یعنی لاَإِلٰہَ إِلاَّ اللّٰہُ پڑھنا) بھی صدقہ ہے، ہر وہ قدم جو نماز کے لیے چلے صدقہ ہے، کسی کو راستہ بتا دو یہ بھی صدقہ ہے، راستہ سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دو یہ بھی صدقہ ہے۔ (الجامع الصغیر)
ایک حدیث میں ہے کہ روزانہ آدمی کے ہر جوڑ کے بدلہ میں اس پر صدقہ ضروری ہے۔ ہر نماز صدقہ ہے، روزہ صدقہ ہے، حج صدقہ ہے، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمد للہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو کوئی راستہ میں مل جائے اس کو سلام کرنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے، برائی سے منع کرنا صدقہ ہے۔ (ابوداود) اور بھی اس قسم کی متعدد روایات وارد ہوئی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر بھلائی، ہر نیکی، ہر احسان صدقہ ہے بشرطے کہ اللہ کے واسطے ہو۔
دوسری چیز حدیث ِبالا میں یہ ذکر کی گئی کہ جو شخص کسی کارِخیر پر کسی کو ترغیب دے اس کو بھی ایسا ہی ثواب ہے جیسا کرنے والے کو۔ یہ حدیث مشہور ہے۔ بہت سے صحابۂ کرام? سے حضور ﷺ کا یہ ارشاد نقل کیا گیا کہ بھلائی کا راستہ بتانے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس کو کرنے والا ہو۔ حق تعالیٰ شا نہٗ عم نوالہٗ کی عطا اور احسان، بخشش اور انعام کا کیا ٹھکانا ہے۔ اس کی عطائیں اس کے الطاف بے محنت ملتے ہیں، مگر ہم لینا ہی نہ چاہیں تو اس کا کیا علاج ہے؟ ایک شخص خود نفلیں کثرت سے نہیں پڑھ سکتا، وہ دوسروں کو ترغیب دے کر نفلیں پڑھوائے اس کوبھی ان کا ثواب ہو۔ خو د نادار ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ما ل کثرت سے خرچ نہیں کرسکتا، دوسروں کو ترغیب دے کر خرچ کرائے اور خرچ کرنے والوں کے ساتھ خود بھی ثواب کا شریک بنے۔ ایک شخص خود روزے نہیں رکھ سکتا، حج نہیں کرسکتا، جہاد نہیں کرسکتا، اور کوئی عبادت نہیں کرسکتا، لیکن ان چیزوں کی دوسروں کو ترغیب دیتا ہے اور خود ان سب کاشریک بنتا ہے۔ بہت غور سے سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ اگر آدمی اپنے آپ ہی ان سب عبادتوں کو کرنے والا ہو تو ایک ہی کے کرنے کا ثواب تو ملے گا، لیکن ان چیزوں پر سو آدمیوں کو ترغیب دے کر کھڑا کر دے تو سو کا ثواب ملے گا۔ اور ہزار دو ہزار کو اور ان سے زیادہ کو لگا دے، تو جتنے لوگوں کو آمادہ کر دے گا سب کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور لطف یہ ہے کہ خود اگر مر بھی جائے گا تو ان اعمال کے کرنے والوں کے اعمال کا ثواب بعد میں بھی پہنچتا رہے گا۔ کیا اللہ کے احسانات کی کوئی حد ہے؟ اور کس قدر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو لاکھوں کو اپنی زندگی میں دینی کاموں پر لگا گئے اور اب مرنے کے بعد وہ ان اعمال کے کرنے والوں کے ثواب میں شریک ہیں۔
میرے چچا جان مولانا مولوی محمد الیاس صاحب نوّر اللہ مرقدہٗ فرمایا کرتے تھے اور مسرت سے فرمایا کرتے تھے کہ لوگ اپنے بعد آدمیوں کو چھوڑ کر جاتے ہیںمیں ملک کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ میوات کا خطہ جہاں لاکھوں آدمی ان کی کوشش سے نمازی بنے، ہزاروں تہجد گزار بنے، ہزاروں حافظِ قرآن، ان سب کا ثواب ان شاء اللہ ان کو ملتا رہے گا۔ اور اب یہ خوش قسمت جماعت عرب اور عجم میں تبلیغ کر رہی ہے۔ ان کی کوشش سے جتنے آدمی کسی دینی کام میں لگ جائیں گے، نماز و قرآن پڑھنے لگیں گے، اس سب کا ثواب ان کوشش کرنے والوں کو بھی ہوگا اور ان کو بھی ہوگا جن کو یہ مسرت تھی کہ میں ملک چھوڑ کر جا رہا ہوں۔
زندگی بہرحال ختم ہونے والی چیز ہے اور مرنے کے بعد وہی کام آتا ہے جو اپنی زندگی میں آدمی کرلے۔ زندگی کے ان لمحات کو بہت غنیمت سمجھنا چاہیے اور جو چیز ذخیرہ بنائی جاسکتی ہو اس میں کسر نہ چھوڑنی چاہیے اور بہترین چیزیں وہ ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہے۔
میرے بزرگو اور دوستو! وقت کو بہت غنیمت سمجھو اور جو ساتھ لے جانا ہے لے جائو، بعد میں نہ کوئی باپ پوچھتا ہے نہ بیٹا، سب چند روز روکر چپ ہو جائیں گے، اور بہترین چیز صدقۂ جاریہ ہے۔
تیسری چیز حدیثِ بالا میں یہ ذکر فرمائی ہے کہ اللہ مصیبت زدہ لوگوں کی فریاد رسی کو پسند کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ اس پر رحم نہیں فرماتے جو آدمیوں پر رحم نہیں کرتا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص مصیبت زدہ عورتوں کی مدد کرتا ہے یا غریب کی مدد کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ جہاد میں کوشش کرنے والا ہو۔ اور غالباً یہ بھی فرمایا کہ وہ ایسا ہے جیسا کہ تمام رات نفلیں پڑھنے والا ہو کہ ذرا بھی سستی نہیں کرتا۔ اور وہ ایسا ہے جیسا کہ ہمیشہ روزہ رکھتا ہو کبھی افطار نہ کرتا ہو۔ (مشکاۃ المصابیح)
ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی مؤمن سے دنیا کی کسی مصیبت کو زائل کرتا ہے اللہ اس سے قیامت کے دن کی مصیبت کو زائل کرتا ہے۔ اور جو شخص کسی مشکل میں پھنسے ہوئے کو سہولت پہنچاتا ہے اللہ اس کو دنیا اور آخرت کی سہولت عطا فرماتا ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کی دنیا میں پردہ پوشی کرتا ہے اللہ دنیا اور آخرت میںاس کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ (مشکاۃ المصابیح)
ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرے اس کوایسا ثواب ہے جیسا کہ حق تعالیٰ شا نہٗ کی تمام عمر خدمت (عبادت) کی ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت کو حاکم تک پہنچائے تو اس کی پلِ صراط پر چلنے میںمددکی جائیگی جس دن کہ اس پر پائوں پھسل رہے ہوں گے۔
ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کو حق تعالیٰ شا نہٗ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ لوگوں کی حاجتیں پوری کیا کریں، ان کے کاموں میںمدد دیا کریں، یہ لوگ قیامت کے سخت دن میں بے فکر ہوںگے، ان کو کوئی خوف نہ ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنے مضطَر بھائی کی مددکرے حق تعالیٰ شا نہٗ اس کو اس دن ثابت قدم رکھیں گے جس دن پہاڑ بھی اپنی جگہ نہ ٹھہر سکیں گے۔ (یعنی قیامت کے دن) ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی کسی کلمہ سے اعانت کرے یا اس کی مدد میں قدم چلائے حق تعالیٰ شا نہٗ اس پر تہتر رحمتیں نازل فرماتے ہیں، جن میں سے ایک میں اس کی دنیا اور آخرت کی درستگی ہے ، اور بہتّر آخرت میں رفعِ درجات کے لیے ذخیرہ ہیں۔
ان کے علاوہ اور بھی بہت سی احادیث اس قسم کے مضامین کی صاحب ’’ِکنز العمال‘‘ نے نقل کی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے میں،ایک دوسرے کے ساتھ تعلق میں، ایک دوسرے پر مہربانی کرنے میں، ایک جسم کی طرح ہیں کہ جب بدن کا کوئی عضو مائوف ہو جاتا ہے تو سارے اَعضا جاگنے میں،بخار میں، اس کاساتھ دیتے ہیں۔ (مشکاۃ المصابیح) یعنی جیسا کہ ایک عضو کی تکلیف سے سارے اَعضا بے چین ہو جاتے ہیں، مثلًا: ہاتھ میں زخم ہو جاتا ہے تو پھر کسی عضو کو بھی نیند نہیں آتی، سب کو جاگنا پڑتا ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ اس کی اَکڑاہٹ سے سارے بدن کو بخار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان کی تکلیف سے سب کو بے چین ہو جانا چاہیے۔
ایک اور حدیث میںہے کہ رحم کرنے والے آدمیوں پررحمن بھی رحم فرماتا ہے۔ تم ان لوگوں پررحم کرو جو دنیا میں ہیں، تم پر وہ رحم کریں گے جو آسمان میں ہیں۔ اس سے حق تعالیٰ شانہٗ بھی مراد ہوسکتے ہیں اور فرشتے بھی۔ ایک حدیث میں ہے کہ مسلمانوں کا بہترین گھر وہ ہے جس میںکوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا برتائو کیا جاتا ہو۔ اوربدترین گھروہ ہے جس میںکوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برُا برتائو کیا جاتا ہو۔ (مشکاۃ المصابیح)
ایک حدیث میں ہے جو شخص میری امت میں سے کسی شخص کی حاجت پوری کرے تاکہ اس کو خوشی ہو، اس نے مجھ کو خوش کیا۔ اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا۔ اور جو شخص حق تعالیٰ شا نہٗ کو خوش کرتا ہے وہ اس کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی مصیبت زدہ آدمی کی مددکرتا ہے اس کے لیے تہتر درجے مغفرت کے لکھے جاتے ہیں، جن میں سے ایک درجہ سے تو اس کی درستگی ہوتی ہے، (یعنی لغزشوں کا بدلہ ہو جاتا ہے) باقی بہتّر درجے رفعِ درجات کا سبب ہوتے ہیں۔
ایک اور حدیث میں ہے کہ مخلوق ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی عیال ہے۔ آدمیوں میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اس کے عیال کے ساتھ اچھا برتائو کرے۔ (مشکاۃ المصابیح)
’’مخلوق ساری کی ساری اللہ کی عیال ہے ‘‘ مشہور حدیث ہے، متعدد صحابہ کرام? سے نقل کی گئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جیسا آدمی اپنے عیال کی روزی کا اہتمام کرنے والا ہوتا ہے، اسی طرح حق تعالیٰ شا نہٗ بھی اپنی ساری مخلوق کے روزی رَساں ہیں۔ اسی لحاظ سے ان کواللہ کے عیال بتایا گیا۔ (مقاصدِحسنہ) اوراس صفت میں مسلمانوں کی بھی خصوصیت نہیں ہے، مسلمان کافر سب ہی شریک ہیں، بلکہ سارے حیوانات اس میںداخل ہیں کہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور اس کے عیال ہیں۔ جو سب کے ساتھ حسنِ سلوک اور اچھا برتائو کرنے والا ہوگا وہ حق تعالیٰ شا نہٗ کو سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔
۲۷۔ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ؓ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰہِ ﷺ یَقُوْلُ: مَنْ صَلَّی یُرَائِيْ فَقَدْ أَشْرَکَ، وَمَنْ صَامَ یُرَائِيْ فَقَدْ أَشْرَکَ، وَمَنْ تَصَدَّقَ یُرَائِيْ فَقَدْ أَشْرَکَ۔
رواہ أحمد کذا في مشکاۃ المصابیح۔
حضورِ اقدسﷺ کا ارشاد ہے کہ جس نے ریا کی نیت سے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ جس نے ریا کے ارادہ سے روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ جس نے ریا کی نیت سے صدقہ دیااس نے شرک کیا۔
فائدہ:
یعنی جس نے ان عبادتوں میںاللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنالیا اور وہ وہ لوگ ہیں جن کو دکھانا مقصود ہے، اس نے اپنی عبادت کو خالص حق تعالیٰ شا نہٗ کے لیے نہیں رکھا، بلکہ اس کی عبادت ساجھے کی عبادت بن گئی اور اس عبادت کی غرض میں ان کا حصہ بھی ہوگیا جن کو دکھانا مقصود ہے۔
یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ اس پر اس فصل کو ختم کرتا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ جو عبادت بھی ہو خالص اللہ کی رضا کے واسطے ہو۔ اس میں کوئی فاسد غرض ریا، شہرت، وجاہت وغیرہ ہرگز نہ ہونا چاہیے کہ اس میں نیکی برباد گناہ لازم ہو جاتا ہے۔ احادیث میں بہت کثرت سے اس پروعیدیں اور تنبیہیں وارد ہوئی ہیں۔
ایک حدیثِ قدسی میں حق سبحانہ و تقدّس کاارشاد وارد ہوا ہے کہ میں سب شریکوں میں سب سے زیادہ بے پرواہ ہوں۔ جو شخص کسی عبادت میں میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کردیتا ہے میںاس عبادت کرنے والے کواس کے (بنائے ہوئے) شریک کے ساتھ چھوڑ دیتا ہوں۔ (مشکاۃ المصابیح) یعنی وہ اپنا بدلہ اور ثواب اس شریک سے جاکر لے لے، مجھ سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔
ایک اور حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن ایک منادی اعلان کرے گا کہ جس شخص نے اپنے کسی عمل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کیا ہے، وہ اس شریک سے اپناثواب مانگ لے، اللہ شرکت سے بے نیاز ہے۔ (مشکاۃ المصابیح)
حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضورﷺ ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم لوگ دجّال کا تذکرہ کررہے تھے۔ حضورِ اقدسﷺ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز بتائوں جس کا میں تم پر دجّال سے بھی زیادہ خوف کرتا ہوں؟ ہم نے عرض کیا کہ ضرور بتائیں۔ حضورﷺ نے فرمایا کہ وہ شرکِ خفی ہے۔ مثلاً: ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، (اخلاص سے شروع کی ہے ، کوئی شخص اس کی نماز کو دیکھنے لگے) وہ آدمی کے دیکھنے کی وجہ سے اپنی نماز لمبی کر دے۔
ایک دوسرے صحابی حضورﷺکا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف چھوٹے شرک کا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا: چھوٹا شرک کیا ہے؟ حضور ﷺنے فرمایا: ریا ہے۔ ایک حدیث میں اس کے بعد یہ بھی ہے کہ جس دن حق تعالیٰ شا نہٗ بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ عطافرمائیں گے، ان لوگوں سے یہ ارشاد ہوگا کہ جن کو دکھانے کے لیے کیے تھے: دیکھو ان کے پاس تمہارے اعمال کا بدلہ ہے یا نہیں۔ (مشکاۃ المصابیح)
قرآن پاک میں بھی حق تعالیٰ شا نہٗ کا پاک ارشاد ہے:
{ فَمَنْ کَانَ یَرْجُوْا لِقَآئَ رَبِّہٖ فَلْیَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلاََ یُشْرِکْ بِعِبَادَۃِ رَبِّہٖ اَحَدًا o} (الکہف : ع ۱۲)
جو شخص اپنے ربّ سے ملنے کی آرزو رکھے (اور ان کا محبوب و مقرب بننا چاہے) تو نیک کام کرتا رہے اور اپنے ربّ کی عبادت میں کسی کوشریک نہ کرے۔
حضرت ابنِ عباس? فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضورﷺ سے دریافت کیا کہ میں بعضے (دینی) مواقع میں اللہ کی رضا کے واسطے کھڑاہوتا ہوں، مگر میرا دل چاہتا ہے کہ میری اس کوشش کولوگ دیکھیں۔ حضورﷺنے اس کا کوئی جواب مرحمت نہیں فرمایا، حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوگئی۔
حضرت مجاہد ؒکہتے ہیں کہ ایک صاحب نے حضورِ اقدسﷺ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں صدقہ کرتا ہوں اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے، مگر دل یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے اچھا کہیں۔ اس پر یہ آیتِ شریفہ نازل ہوئی۔
ایک حدیثِ قدسی میں ہے حق تعالیٰ شا نہٗ کاارشاد ہے کہ جو شخص اپنے عمل میں میرے ساتھ کسی دوسرے شخص کو شریک کرتا ہے تو میں اس عمل کو سارے ہی کو چھوڑ دیتا ہوں۔ میں صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہوں جو خالص میرے لیے ہو۔ اس کے بعد حضور ﷺ نے یہ آیتِ شریفہ تلاوت فرمائی۔ ایک اور حدیث میں ہے: اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ساتھی کے ساتھ بہترین تقسیم کرنے والا ہوں۔ جو شخص اپنی عبادت میں میرے ساتھ کسی دوسرے کو ساجھی کر دے میں اپنا حصہ بھی اس ساجھی کو دے دیتا ہوں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جہنم میںایک وادی ایسی ہے جس سے جہنم خودبھی چار سو مرتبہ روزانہ پناہ مانگتی ہے، وہ ریاکار قاریوں کے واسطے ہے۔
ایک اور حدیث میںحضورِ اقدسﷺ کا ارشاد آیا ہے کہ جُبُّ الْحُزْن سے پناہ مانگا کرو۔ (یعنی غم کے کنوئیں سے جو جہنم میں ہے) صحابہ نے عرض کیا: یارسول اللہ! اس میں کون لوگ رہیں گے؟ حضورﷺنے فرمایا کہ جو اپنے اعمال میں ریاکاری کرتے ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ یہ آیتِ شریفہ قرآنِ پاک میں سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ (دُرِّمنثور) قرآن پاک میں دوسری جگہ ارشاد ہے:
{یٰٓـاَیُّھَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَاتُبْطِلُوْا صَدَقٰـتِکُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰی لا کَالَّذِیْ یُنْفِقُ مَالَہٗ رِئَآئَ النَّاسِ (الآیۃ)}
( البقرۃ : ع ۳۶)
اے ایمان والو! تم احسان جتاکر یا اِیذا پہنچا کر اپنی خیرات کو برباد مت کرو، جس طرح وہ شخص (برباد) کرتا ہے جو اپنا مال لوگوں کو دکھلانے کی غرض سے خرچ کرتا ہے، اور ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور قیامت کے دن پر، اس شخص کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک چکنا پتھر ہو جس پرکچھ مٹی آگئی ہو (اور اس مٹی میں کچھ سبزہ وغیرہ جم گیا ہو)، پھر اس پتھر پرزور کی بارش پڑ جائے سو وہ اس کو بالکل صاف کر دے گی، (اسی طرح ان احسان رکھنے والوں، اِیذا دینے والوں اور ریاکاروں کا خرچ کرنا بھی بالکل صاف اُڑ جائے گا اور قیامت کے دن) ایسے لوگوں کو اپنی کمائی ذرا بھی ہاتھ نہ لگے گی۔ (یعنی یہ جو نیکیاں کی تھیں صدقات دیے تھے یہ سب ضائع جائیںگے)
اس کے علاوہ اور بھی کئی جگہ قرآنِ پاک میں ریا کی مذمت فرمائی ہے۔ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کا فیصلہ ہوگا ان میںایک تو شہید ہوگا، اس کو بلایا جائے گا اور بلانے کے بعددنیا میں جو اللہ کے انعامات اس پرہوئے تھے وہ اس کو یاد دلائے جائیں گے۔ اس کے بعد اس سے مطالبہ ہوگا کہ اللہ کی ان نعمتوں میں رہ کر تو نے کیا نیک عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا کہ میں نے تیری رضا جُوئی میں جہاد کیا حتیٰ کہ شہید ہوگیااور تجھ پر قربان ہوگیا۔ ارشاد ہوگاکہ یہ جھوٹ ہے، تُو نے جہاد اس لیے کیا تھا کہ لوگ بڑا بہادر بتائیں گے، وہ تجھے بہت بڑا بہادر بتا چکے۔ (جو غرض عمل کی تھی وہ پوری ہو گئی ہے) اس کے بعد اس کوجہنم میں پھینک دینے کاحکم کیا جائے گا اورتعمیلِ حکم میں اس کومنہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔
دوسرا شخص ایک عالم ہوگا جس کو بلا کر اللہ کے انعامات اور احسانات جتا کر اس سے بھی دریافت کیا جائے گا کہ اللہ کی ان نعمتوں میں تو نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے علم سیکھا اور لوگوں کو سکھایا، تیری رضا جوئی میں قرآن پاک پڑھتا رہا۔ ارشاد ہوگا: یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب کچھ اس لیے کیاگیا تھاکہ لوگ کہیں گے کہ فلاں شخص بڑا عالم، بڑا قاری ہے، سو لوگوں نے کہہ دیا ہے۔ (اور جو مقصد اس محنت سے تھا وہ حاصل ہوچکا ہے) اس کے بعد اس کوبھی جہنم میں پھینکنے کا حکم کیاجائے گا اور تعمیلِ حکم میں منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیاجائے گا۔ تیسرا شخص ایک سخی ہوگا جس پراللہ نے دنیا میں بڑی وسعت فرما رکھی تھی، ہر قسم کے مال سے اس کو نوازا تھا، اس کو بلایا جائے گا اور جوا نعامات اللہ نے اس پر دنیا میں فرمائے تھے وہ جتا کرسوال کیا جائے گا کہ ان انعامات میں تیری کیاکارگزاری ہے؟ وہ عرض کرے گا کہ میں نے خیر کا کوئی موقع جس میں خرچ کرنا آپ کوپسند ہو ایسا نہیں چھوڑا جس میں آپ کی خوشنودی کے لیے خرچ نہ کیا ہو۔ ارشاد ہوگا: یہ جھوٹ ہے، تو نے محض اس لیے خرچ کیا کہ لوگ کہیںگے بڑا سخی شخص ہے، سو کہا جاچکا ہے ۔ اس کے بعداس کوبھی جہنم میں پھینکنے کا حکم ہوگا اور تعمیلِ حکم میں منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ (مشکاۃ المصابیح بروایۃ مسلم)
اس حدیث میں، اور اسی طرح اور احادیث میںجہاں ایک شخص کا ذکرآتا ہے اس سے ایک قسم آدمیوںکی مراد ہوتی ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ یہ معاملہ صرف تین آدمیوں کے ساتھ کیا جائے گا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ تینوں قسم کے آدمیوں سے یہ مطالبہ ہوگا اورمثال کے طور پر ہر قسم میں سے ایک ایک آدمی کا ذکر کر دیا۔
ان کے علاوہ اور بھی احادیث میں کثرت سے اس پر تنبیہ کی گئی ہے اور بہت زیادہ اہمیت سے حضورِ اقدسﷺ نے اپنی امت کو اس پر متنبّہ کیا ہے کہ جو کام بھی کیاجائے وہ خالص اللہ کے لیے کیا جائے، اور جتنا بھی اہتمام ہوسکے اس کاکیا جائے کہ اس میں ریااور نمود وشہرت اور دکھاوے کا شائبہ بھی نہ آنے پائے، مگراس جگہ شیطان کے ایک بڑے مکر سے بے فکر نہ ہونا چاہیے۔ دشمن جب قوی ہوتا ہے وہ مختلف انواع سے اپنی دشمنی نکالا کرتا ہے۔ یہ بہت مرتبہ آدمی کو اس وسوسہ کی بدولت کہ اخلاص تو ہے ہی نہیں، اہم ترین عبادتوں سے روک دیاکرتا ہے۔
امام غزالی ؒ فرماتے ہیں کہ شیطان اوّل تو نیک کام سے روکا کرتا ہے اور ایسے خیالات دل میں ڈالا کرتا ہے جس سے اس کام کے کرنے کا ارادہ ہی پیدا نہ ہو، لیکن جب آدمی اپنی ہمت سے اس کامقابلہ کرتا ہے اور اس کے روکنے پر عمل نہیں کرتا تو وہ کہاکرتا ہے تجھ میں اخلاص توہے ہی نہیں، یہ تیری عبادت محنت بے کار ہے، جب اخلاص ہی نہیں پھر ایسی عبادت کرنے سے کیا فائدہ؟ اور اس قسم کے وسوسے پیدا کرکے نیک کام سے روک دیا کرتا ہے۔ اور جب آدمی رک جاتا ہے تو اس کی غرض پوری ہو جاتی ہے۔ (اِحیاء العلوم) اس لیے اس خیال سے نیک کام کرنے سے رکنا نہیں چاہے کہ اخلاص تو ہے ہی نہیں، بلکہ نیک کام کرنے میں اخلاص کی کوشش کرتے رہنا چاہیے اور اس کی دعاکرتا رہے کہ حق تعالیٰ شا نہٗ محض اپنے لطف سے دستگیری فرمائے تاکہ نہ تو دین کا مشغلہ ضائع ہو، نہ برباد ہو۔
وَمَا ذٰلِکَ عَلَی اللّٰہِ بِعَزِیْزٍ
دوسری فصل
بخل کی مذمت میں
پہلی فصل میں جتنی آیات اور احادیث اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے کی گزر چکی ہیں ان سے خود ہی یہ بات ظاہر ہوگئی کہ جب اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے کے اتنے فضائل وفوائد اور خوبیاں ہیں تو جتنی اس میں کمی ہوگی یہ منافع حاصل نہ ہوں گے۔ یہ خود ہی کافی مذمت اِنتہائی نقصان ہے، لیکن اللہ اور اس کے پاک رسولﷺ نے تنبیہ اور اہتمام کی وجہ سے بخل اور مال کو روک کر رکھنے پرخصوصی وعیدیں بھی ارشاد فرمائی ہیں، جو اللہ کا انعام اور اس کے پاک رسول کی امت پر اتنہائی شفقت ہے کہ اس نے اس مہلک مرض پر خاص طور سے بہت سی تنبیہیں فرما دیں۔ قرآن و حدیث میں ہر مضمون نہایت ہی کثرت سے ذکر کیا گیا اور مختلف عنوانوں سے ہرخیر کے کرنے پر ترغیب اور ہر برائی سے رکنے پر تنبیہیں کی گئیں۔ کسی ایک مضمون کا اِحاطہ بھی دشوار ہے۔ نمونہ کے طور پر اس کے متعلق بھی چند آیات اور چند احادیث لکھی جاتی ہیں۔
آیات:
۱۔ وَاَنْفِقُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰہِ وَلاََ تُلْقُوْا بِاَیْدِیْکُمْ اِلَی الْتَّھْلُکَۃِ ج
(البقرۃ : ع ۲۴)
تم لوگ اللہ کے راستہ میں خرچ کیاکرو اوراپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔
فائدہ:
یہ آیتِ شریفہ پہلی فصل کے سلسلۂ آیات میں نمبر (۳) پرگزر چکی ہے۔ اس آیتِ شریفہ میں اللہ کے راستہ میں خر چ نہ کرنے کواپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت اور تباہی میں ڈالنا قرار دیا ہے جیساکہ پہلے مفصل صحابہ کرام ? سے نقل کیا جاچکا ہے۔ کون شخص ہے جو اپنی تباہی اوربربادی چاہتا ہو؟ مگر کتنے آدمی ہیں جو یہ معلوم ہو جانے کے باوجود کہ یہ تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے اس سے بچتے ہیں اور مال کو جوڑ جوڑ کر نہیں رکھتے۔ اس کے سوا کیا ہے کہ غفلت کا پردہ ہم لوگوں کے دلوں پر پڑا ہوا ہے اور اپنے ہاتھوں ہی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے جا رہے ہیں۔
۲۔ اَلشَّیْطَانُ یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ وَیَاْمُرُکُمْ بِالْفَحْشَآئِ ج وَاللّٰہُ یَعِدُکُمْ مَّغْفِرَۃً مِّنْہُ وَ فَضْلاً ط وَاللّٰہُ وَاسِعٌ عَلِیْمٌ o (البقرۃ : ع ۳۷)
شیطان تم کو محتاجی (اور فقر) سے ڈراتا ہے اور تم کو بری بات (بخل) کا مشورہ دیتا ہے، اوراللہ تعالیٰ تم سے (خرچ کرنے پراپنی طرف سے) گناہ معاف کر دینے کا اور زیادہ دینے کا
وعدہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں، (وہ سب کچھ دے سکتے ہیں) خوب جاننے والے ہیں۔ (نیت کے موافق ثمرہ دیتے ہیں)
فائدہ: حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں: حضورِ اقدسﷺ نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے اندر ایک تو شیطان تصرُّف کرتا ہے اور ایک فرشتہ تصرُّف کرتا ہے۔ شیطان کا تصرُّف تو برائی کے ساتھ ڈرانا ہے (مثلاً صدقہ کرے گا تو فقیرہو جائے گا وغیرہ وغیرہ) اور حق بات کا جھٹلانا ہے، اور فرشتہ کا تصرُّف بھلائی کاوعدہ کرنا ہے اور حق بات کی تصدیق کرنا ہے۔ جو اس کوپاوے (یعنی بھلائی کی بات کا خیال دل میںآوے تو اس کو) اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھے اور اس کا شکر ادا کرے، اور جو دوسری بات کو پاوے (یعنی براخیال دل میں آوے) تو شیطان سے پناہ مانگے۔ اس کے بعد حضورِ اقدسﷺ نے یہ آیتِ شریفہ پڑھی۔ (مشکاۃ المصابیح)
یعنی حضورِ اقدسﷺ نے اپنے ارشاد کی تائید میں یہ آیتِ شریفہ پڑھی جس میں حق تعالیٰ شا نہٗ کا ارشاد ہے کہ شیطان فقر کا خوف اور فحش باتوں کی ترغیب دیتا ہے اوریہی حق کا جھٹلانا ہے۔
حضرت ابنِ عباس? فرماتے ہیں کہ اس آیتِ شریفہ میں دو چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں اور دو چیزیں شیطان کی طرف سے ہیں۔ شیطان فقر کا وعدہ کرتا ہے اوربری بات کا حکم کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ مال خرچ نہ کر، احتیاط سے رکھ تجھے اس کی ضرورت پڑے گی، اور اللہ ان گناہوں پر مغفرت کا وعدہ فرماتا ہے اوررزق میں زیادتی کا وعدہ فرماتا ہے۔ (دُرِّمنثور)
امام غزالی ؒفرماتے ہیں کہ آدمی کو آیندہ کے فکر میں زیادہ مبتلا نہیں رہنا چاہیے کہ کیا ہوگا، بلکہ جب حق تعالیٰ شا نہٗ نے رزق کا وعدہ فرما رکھا ہے تو اس پر اعتماد کرنا چاہیے اور یہ سمجھتے رہنا چاہیے کہ آیندہ کی اِحتیاج کا خوف شیطانی اثر ہے، جیسا کہ اس آیتِ شریفہ میں بتایا گیا۔ وہ آدمی کے دل میں یہ خیال پکاتا رہتا ہے کہ اگر تو مال جمع کرکے نہیں رکھے گاتو جس وقت تو بیمار ہو جائے گا یا کمانے کے قابل نہیںرہے گا یا کوئی اور وقتی ضرورت پیش آجائے گی تواس وقت تو مشکل میں پھنس جائے گا، اور تجھے بڑی دِقّت اور تکلیف ہوگی۔ اور ان خیالات کی وجہ سے اس کو اس وقت مشقت اور کوفت اور تکلیف میں پھانس دیتا ہے، اورہمیشہ اسی تکلیف میں مبتلا رکھتا ہے، اور پھر اس کا مذاق اڑاتا ہے کہ یہ احمق آیندہ کی موہوم تکلیف کے ڈر سے اس وقت کی یقینی تکلیف میں پھنس رہا ہے۔ (اِحیاء العلوم) کہ جمع کی فکر میںہر وقت پریشان رہتا ہے اور آیندہ کا فکر سوار رہتا ہے۔
۳۔ وَلَا یَحْسَبَنَّ الَّذِیْنَ یَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰـھُمُ اللّٰہُ مِنْ فَضْلِہٖ ھُوَ خَیْرًا لَّھُمْط بَلْ ھُوَشَرٌّ لَّھُمْط سَیُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِہٖ یَوْمَ الْقِیٰمَۃِط وَلِلّٰہِ مِیْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَاللّٰہُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِیْرٌo
(آل عمران: ع ۱۸)
ہرگز خیال نہ کریں ایسے لوگ جو ایسی چیز کے خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں جو ان کو اللہ نے محض اپنے فضل سے عطا کی ہے کہ یہ بات (یعنی بخل کرنا) ان کے لیے کچھ اچھی ہوگی، (ہرگز نہیں) بلکہ یہ بات اُن کے لیے بہت بری ہوگی، ا س لیے کہ وہ لوگ قیامت کے دن طوق پہنائے جائیں گے
اس مال کا جس کے ساتھ بخل کیا تھا، (یعنی سانپ بناکر ان کی گردنوں میں ڈال دیا جائے گا) اور اَخیر میں آسمان و زمین (اور جو کچھ ا ن کے اندر ہے، لوگوں کے مرجانے کے بعد) اللہ ہی کا رہ جائے گا (تم اپنے ارادہ سے اس کو دے دو تو ثواب بھی ہو ورنہ ہے تو اسی کا) اورا للہ تمہارے سارے اعمال سے خبردار ہیں۔
فائدہ: ’’بخاری شریف‘‘ میں حضورِ اقدسﷺ کا پاک ارشاد وارد ہوا ہے کہ جس شخص کو اللہ نے مال عطاکیا ہو اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو تو وہ مال قیامت کے دن ایک گنجا سانپ (جس کے زہر کی کثرت اور شدت کی وجہ سے اس کے سرکے بال بھی جاتے رہے ہوں) بنایا جائے گا، جس کے منہ کے نیچے دو نقطے ہوں گے (یہ بھی زہر کی زیادتی کی علامت ہے) اور وہ سانپ اس کے گلے میں ڈال دیاجائے گا، جو اس شخص کے دونوں جبڑے پکڑ لے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں،میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد حضورِ اقدسﷺ نے یہ آیتِ شریفہ تلاوت فرمائی۔ (مشکاۃ المصابیح)
یہ حدیث شریف زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وعیدوں میں پانچویں فصل کی احادیث میں نمبر(۲) پر آرہی ہے۔ حضرت حسن بصری ؒ فرماتے ہیںکہ یہ آیتِ شریفہ کافروں کے بارے میں اور اس مؤمن کے بارے میں جو اپنے مال کو اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے سے بخل کرتا ہو نازل ہوئی ہے۔ عِکرمہ ؒ کہتے ہیں کہ مال میں سے جب اللہ کے حقوق ادا نہ ہوتے ہوں تو وہ مال گنجا سانپ بن کر قیامت میں اس کے پیچھے لگ جائے گا اور وہ آدمی اس سانپ سے پناہ مانگتا ہوا ہوگا۔
حجر بن بیانؓحضور ﷺکا ارشاد نقل کرتے ہیںکہ جو ذی رحم اپنے قریبی رشتہ دار سے اس کی ضرورت سے بچے ہوئے مال سے مدد مانگے، اور وہ مدد نہ کرے اور بخل کرے، تو وہ مال قیامت کے دن سانپ بنا کر اس کو طوق پہنا دیا جائے گا، اور پھر حضورِ اقدسﷺ نے یہ آیتِ شریفہ تلاوت فرمائی۔ اور متعدد صحابہ کرام? سے بھی یہ مضمون نقل کیا گیا۔
مسروق ؒکہتے ہیں کہ یہ آیتِ شریفہ اس شخص کے بارے میں ہے جس کو اللہ نے مال عطا کیا اور وہ اپنے رشتہ داروں کے ان حقوق کو جو اللہ نے اس پر رکھے ہیں، ادا نہ کرے ، تو اس کا مال سانپ بنا کر اس کو طوق پہنا دیا جائے گا۔ وہ شخص اس سانپ سے کہے گا کہ تو نے میرا پیچھا کیوں کیا؟ وہ کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں۔ (دُرِّمنثور)
اما م رازی ؒ ’’تفسیرِ کبیر ‘‘میں تحریر فرماتے ہیں کہ اوپر کی آیات میں جہاد میں اپنی جانوں کی شرکت پر تاکید و ترغیب تھی۔ اس کے بعد اس آیت میں جہاد میں مال خرچ کرنے کی تاکید ہے۔ او رتنبیہ ہے کہ جو لوگ جہاد میں مال خرچ نہیں کرتے تو وہ مال سانپ بن کر ان کے گلے کا ہار بن جائے گا۔ اور اس کے بعد امام رازی ؒ طویل بحث اس پر کرتے ہیں کہ جو شدید و عید اس آیتِ شریفہ میں ہے وہ تطوُّعات کے ترک پر تو مشکل ہے، ترکِ واجب پر ہی ہو سکتی ہے۔ البتہ واجبات کئی قسم کے ہیں۔ اوّل اپنے اوپر اور اپنے ان اقارب پر خرچ کرنا جن کا نفقہ اپنے ذمہ واجب ہے۔ دوسرے زکوٰۃ۔ تیسرے جس وقت مسلمانوں پر کفار کا ہجوم ہو کہ وہ ان کے جان و مال کو ہلاک کرنا چاہتے ہوں، تو اس وقت سب مال داروں پر حسبِ ضرورت خرچ کرنا واجب ہے، جس سے مدافعت کرنے والوں کی مدد ہو کہ یہ دراصل اپنی ہی جان و مال کی حفاظت میں خرچ ہے۔ چوتھے مضطَر پر خرچ کرنا ہے جس سے اس کی جان کا خطرہ زائل ہو جائے۔ یہ سب اخراجات واجب ہیں۔
۴۔ اِنَّ اللّٰہَ لَایُحِبُّ مَنْ کَانَ مُخْتَالاً فَخُوْرَانِ o الَّذِیْنَ یَبْخَلُوْنَ وَیَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالبُخْلِ وَیَکْتُمُوْنَ مَآ اٰتٰھُمُ اللّٰہُ مِنْ فَضْلِہٖط وَاَعْتَدْنَا لِلْکَفِرِیْنَ عَذَابًا مُّھِیْنًا o (النساء : ع ۴)
بے شک اللہ ایسے آدمیوں کو پسند نہیں کرتا جو (دل میں) اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوں۔ (زبان سے شیخی کی باتیں کرتے ہوں۔) جو خود بھی بخل کرتے ہوں اور دوسروں کو بخل کی تعلیم دیتے ہوں۔
اور جو چیز اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے اس کو چھپاتے ہوں، اورہم نے ایسے ناشکروں کے لیے اِہانت والا عذاب تیار کررکھا ہے۔
فائدہ: ’’دوسروں کو بخل کی تعلیم دیتے ہوں‘‘ عام ہے کہ زبان سے ان کوترغیب دیتے ہوں یا اپنے عمل سے تعلیم دیتے ہوں کہ ان کے عمل کو دیکھ کر دوسروں کو بخل کی ترغیب ہوتی ہو۔ بہت سی احادیث میں یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ جو شخص برا طریقہ اختیار کرتا ہے اس کو اپنے کیے کا وبال بھی ہوتا ہے اور جتنے آدمی اس کی وجہ سے اس پر عمل کریں ان سب کا گناہ بھی اس کوہوتا ہے، اس طرح پر کہ ان کو اپنی اپنی سزائوں میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ یہ مضمون قریب ہی مفصل گزر چکا ہے۔
حضرت مجاہد ؒ سے ’’مُخْتَالاً فَخُوْرًا‘‘کی تفسیر میں نقل کیا گیا کہ یہ ہر وہ متکبر ہے جو اللہ کی عطا کی ہوئی چیزوں کو گن گن کررکھتا ہے اور اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ حضرت ابو سعید خدریؓ حضورِ اقدسﷺ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جب حق تعالیٰ شا نہٗ ساری مخلوق کو ایک جگہ جمع فرما دیں گے توجہنم کی آگ تَوبتَو چڑھتی ہوئی ان کی طرف شدت سے بڑھے گی۔ جو فرشتے اس پر متعین ہیں وہ اس کو روکنا چاہیں گے تووہ کہے گی کہ میرے ربّ کی عزت کی قسم! یا تو مجھے چھوڑ دو کہ میں اپنے جوڑی داروں (یاروں) کو لے لوں، ورنہ میں سب پر چھا جائوں گی۔ وہ پوچھیں گے: تیرے جوڑی دارکون ہیں؟ وہ کہے گی: ہر متکبر ظالم۔ اس کے بعد جہنم اپنی زبان نکالے گی اور ہر ظالم متکبر کو چن چن کر اپنے پیٹ میں ڈال لے گی (جیسا کہ جانور زبان کے ذریعہ سے گھاس کھاتا ہے) ان سب کو چن کر پیچھے ہٹ جائے گی۔ اس کے بعد اسی طرح دوبارہ زورکرکے آئے گی اور یہ کہے گی کہ مجھے اپنے جوڑی داروں کو لینے دو۔ اور جب اس سے پوچھاجائے گا کہ تیرے جوڑی دارکون ہیں؟ تو وہ کہے گی: ہر اَکڑنے والا، ناشکری کرنے والا۔ اور پہلے کی طرح ان کو بھی چن کر اپنی زبان کے ذریعہ سے اپنے پیٹ میں ڈال لے گی۔ پھر اسی طرح جوش کرکے چلے گی اور اپنے جوڑی داروں کامطالبہ کرے گی اور جب اس سے پوچھا جائے گا کہ تیرے جوڑی دارکون لوگ ہیں؟ تو وہ اس مرتبہ کہے گی: ہر اَکڑنے والا، فخر کرنے والا۔ اور ان کو بھی چن کر اپنے پیٹ میں ڈال لے گی۔ اس کے بعد لوگوں کا حساب کتاب ہوتا رہے گا۔
حضرت جابر بن سُلیم ہجیمیؓفرماتے ہیں کہ میں حضورِ اقدسﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مدینہ منورہ کی ایک گلی میں چلتے ہوئے حضورﷺسے ملاقات ہوگئی۔ میں نے سلام کیا اور لنگی کے متعلق مسئلہ دریافت کیا۔ حضورﷺ نے فرمایا کہ پنڈلی کے موٹے حصے تک ہونی چاہیے، اور اگر تجھے اتنی اونچی پسند نہ ہو تو تھوڑی اور نیچے تک سہی، اور یہ بھی پسند نہ ہو تو ٹخنوں کے اوپر تک، اور یہ بھی پسند نہ ہو تو (آگے گنجایش نہیں اس لیے کہ ) اللہ متکبر فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ (اور ٹخنوں سے نیچے لنگی یا پاجامہ کو لٹکانا تکبر میں داخل ہے) پھر میں نے کسی کے ساتھ احسان اوربھلائی کرنے کے متعلق دریافت کیا۔ حضورﷺ نے فرمایا کہ بھلائی کو حقیر نہ سمجھو (کہ اس وجہ سے ملتوی کر دو) چاہے رسی کاٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، جوتے کاتسمہ ہی کیوں نہ ہو۔ کسی پانی مانگنے والے کے برتن میں پانی کا ڈول ہی ڈال دو۔ راستہ میں کوئی اَذیت پہنچانے والے چیز ہو اس کو ہٹا دو۔ حتیٰ کہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے بات ہی سہی، راستہ چلنے والے سے سلام ہی سہی، کوئی گھبرا رہا ہو اس کی دل بستگی ہی سہی۔ (کہ یہ سب چیزیں احسان اور نیکی میں داخل ہیں) اور اگر کوئی شخص تمہارے عیب کو ظاہر کرے اور تمہیں اس کے اندر کوئی دوسرا عیب معلوم ہے تو تم اس کو ظاہر نہ کرو۔ تمہیں اس اِخفا کاثواب ملے گا، اس کو اس اِظہار کا گناہ ہوگا۔اور جس کام کو تم یہ سمجھو کہ کسی کو اس کی خبر ہوگئی تو مضائقہ نہیں، اس کو کرو۔ اور جس کو تم یہ سمجھو کہ کسی کو اس کی خبر نہ ہو، اس کو نہ کرو۔ (یہ علامت اس کے برا ہونے کی ہے)
حضرت عبداللہ بن عباس? فرماتے ہیں کہ کَرْدم بن یزید وغیرہ بہت سے آدمی انصار کے پاس آتے اور ان کو نصیحت کرتے کہ اتنا خرچ نہ کیاکرو، ہمیں ڈر ہے کہ یہ سب خرچ ہو جائے گا تم فقیر بن جائوگے، ہاتھ روک کر خرچ کیا کرو، نہ معلوم کہ کل کو کیا ضرورت پیش آجائے۔ ان لوگوں کی مذمت میں یہ آیتِ شریفہ نازل ہوئی۔ (دُرِّمنثور)
۵۔ وَالَّذِیْنَ یَکْنِزُوْنَ الذَّھَبَ وَالْفِضَّۃَ وَلَا یُنْفِقُوْنَھَا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰہِ فَبَشِّرْھُمْ بِعَذَابٍ اَلِیْمٍ o یَّوْمَ یُحْمٰی عَلَیْھَا فِیْ نَارِجَھَنَّمَ فَتُکْوٰی بِھَا جِبَاھُھُمْ وَجُنُوْبُھُمْ وَظُھُوْرُھُمْ ط ھٰذَا مَا کَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِکُمْ فَذُوْقُوْا مَا کُنْتُمْ تَکْنِزُوْنَ o (التوبۃ : ع ۵)
جو لوگ سونا چاندی جمع کرکے خزانہ کے طور پر رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی را ہ میں خرچ نہیں کرتے، آپ ان کو بڑے دردناک عذاب کی خوش خبری سنا دیجیے۔ وہ اس دن ہوگا جس دن ان کو (سونے چاندی کو) اوّل جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر ان سے ان لوگوںکی پیشانیوں اور پسلیوں اور
پشتوں کو داغ دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ و ہ ہے جس کو تم نے اپنے واسطے جمع کرکے رکھا تھا، اب اس کامزہ چکھو جس کو جمع کرکے رکھا تھا۔
فائدہ:
علماء نے لکھا ہے کہ پیشانیوں وغیرہ کے ذکر سے آدمی کی چاروں طرف مراد ہیں۔ پیشانی سے اگلا حصہ، پسلیوں سے دایاں اوربایاں، اور پشت سے پچھلا حصہ مراد ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ سارے بدن کو داغ دیا جائے گا۔ ایک حدیث سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے جس میںمنہ سے قدم تک داغ دیا جانا وارد ہوا ہے۔
اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ ان تینوں اَعضا کی خصوصیت اس لیے ہے کہ ان میں ذرا سی تکلیف بھی زیادہ محسو س ہوتی ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ ان تین کو اس وجہ سے ذکر کیا کہ آدمی جب چہرہ سے فقیر کو دیکھتا ہے تو پہلو بچا کر اس طرف پشت کرکے چل دیتا ہے، اس لیے ان تینوں اَعضا کو خصوصیت سے عذاب ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی وجو ہ ذکر کی گئیں۔ (تفسیرِ کبیر)
اس آیتِ شریفہ میں اس مال کو تپا کر داغ دینا وارد ہے اور آیت نمبر(۳ ) پر اس کا سانپ بن کر پیچھے لگنا وارد ہوا ہے، ان دونوں میں کچھ اِشکال نہیں، یہ دونوں عذاب علیحدہ علیحدہ ہیں، جیسا کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے بیان میں پانچویں فصل کی حدیث نمبر (۲) پر آرہاہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس? اور متعدد صحابہ کرام? سے نقل کیا گیا کہ اس آیتِ شریفہ میں خزانہ سے مراد وہ مال ہے جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہو اور جس کی زکوٰۃ اداکر دی گئی ہو وہ خزانہ نہیں ہے۔ حضرت ابنِ عمر? سے نقل کیا گیا کہ یہ حکم زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے سے پہلے تھا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوگیا تو حق تعالیٰ شا نہٗ نے زکوٰۃ اداکر دینے کو بقیہ مال کے پاک ہو جانے کا سبب قرار دیا۔
حضرت ثوبانؓ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیتِ شریفہ نازل ہوئی تو ہم حضورِاقدسﷺ کے ساتھ ایک سفر میں تھے، تو بعض صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! سونا چاندی جمع کرنے کا تویہ حشر ہے۔ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ بہترین مال کیا ہے جس کو خزانہ کے طور پر جمع کرکے رکھیں۔ حضورﷺ نے فرمایا: اللہ کا ذکر کرنے والی زبان، اللہ کا شکر ادا کرنے والا دل اور نیک بیوی جو آخرت کے کاموں میں مدد دیتی رہے۔
حضرت عمرؓ سے نقل کیا گیا کہ جب یہ آیتِ شریفہ نازل ہوئی تو وہ حضورﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یہ آیتِ شریفہ تولوگوں پربہت بار ہو رہی ہے۔ حضورﷺ نے فرمایا کہ اللہ نے زکوٰۃ اسی لیے مشروع فرمائی ہے کہ بقیہ مال پاک ہو جائے اور میراث تو اسی مال میںجاری ہوگی جو بعد میں باقی رہے، اور بہترین چیز جس کو آدمی خزانہ کی طرح محفوظ رکھے وہ نیک بیوی ہے جس کو دیکھ کر جی راضی ہو جائے، جب اس کو کوئی حکم کیا جائے فوراً اطاعت کرے اور جب خاوند غائب ہو (سفر وغیرہ میں) تواپنی (اور اس کے مال کی) حفاظت کرے۔
حضرت بریدہؓ فرماتے ہیں: جب یہ آیتِ شریفہ نازل ہوئی تو صحابہ ? میں اس کا چرچا ہوا۔ حضرت ابوبکرؓ نے حضورﷺ سے دریافت کیا: یارسول اللہ! خزانہ بنانے کے لیے کیا چیز بہتر ہے؟ حضورﷺنے فرمایا: ذکر کرنے والی زبان ، شکر کرنے والا دل اور وہ نیک بیوی جو ایمانی چیزوں پر مدد کرے۔
حضرت ابوذرؓ حضورِ اقدسﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ جو شخص دینار (سونے کاسکہ) دِرَم (چاندی کا سکہ) یا سونے چاندی کا ٹکڑا رکھے گا اور اللہ کے راستہ میں خرچ نہ کرے گا بشرطے کہ قرض کے ادا کرنے کے واسطے نہ رکھا ہو، وہ خزانہ میں داخل ہے، جس کا قیامت کے دن داغ دیا جائے گا۔ حضرت ابوامامہؓ حضورِ اقدسﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ جو شخص سونا یا چاندی چھوڑ کر مر جائے اس کاقیامت کے دن داغ دیا جائے گا، بعد میں چاہے جہنم میں جائے یامغفرت ہو جائے۔
حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضورِاقدسﷺ کا ارشاد نقل کرتے کہ اللہ نے مسلمانوں کے اَغنیا کے مالوں میں وہ مقدار فر ض کر دی ہے جوان کے فقرا کو کافی ہے۔ فقرا کو بھوکے یا ننگے ہونے کی مشقت صرف اسی وجہ سے پڑتی ہے کہ اَغنیا ان کو دیتے نہیں۔ خبردار رہو کہ حق تعالیٰ شا نہٗ قیامت کے دن ان اَغنیا سے سخت مطالبہ کریں گے یا سخت عذاب دیں گے۔ (دُرِّمنثور) ’’کنز العمال‘‘ میں اس حدیث پر کلام بھی کیا ہے اور حضرت ابوہریرہؓکی حدیث سے نقل کیا کہ اگر اللہ کے علم میںیہ بات ہوتی کہ اَغنیا کی زکوٰۃ فقرا کو کافی نہ ہوگی، تو زکوٰۃ کے علاوہ اور کوئی چیز ان کے لیے تجویز فرماتے جو ان کو کافی ہو جاتی۔ پس اب جوفقرا بھوکے ہیں وہ اَغنیا کے ظلم کی وجہ سے ہیں۔ (کنز العمال) کہ وہ پوری زکوٰۃ نہیں نکالتے۔
حضرت بلالؓ سے نقل کیاگیا کہ حضورﷺ نے اُن سے ارشاد فرما: اللہ تعالیٰ سے فقر کی حالت میں ملو، تونگری کی حالت میں نہ ملو۔ انھوںنے عرض کیا: اس کی کیا صورت ہے؟ حضورﷺ نے فرمایا کہ جب کہیں سے کچھ میسر ہو اس کو چھپا کر نہ رکھو، مانگنے والے سے انکار نہ کرو۔ انھوں نے عرض کیا: حضور! یہ کیسے ہوسکتا ہے؟ حضورﷺ نے فرمایا: یہی ہے، او ر یہ نہ ہو تو جہنم ہے۔ (دُرِّمنثور) حضر ت ابوذر غفاریؓ بھی انہی حضرات میں ہیں جن کامسلک یہ ہے کہ روپیہ پیسہ بالکل رکھنے کی چیز نہیں ہے۔ ایک دِرَم جہنم کا ایک داغ ہے اور دو دِرَم دو داغ ہیں۔ ان کے مختلف واقعات پہلے گزر چکے ہیں جن میں سے بعض پہلی فصل کے سلسلۂ احادیث میں نمبر (۱) پر گزرے۔
ایک مرتبہ حبیب بن سلمہ ؒ نے جو شام کے امیر تھے حضرت ابوذرؓ کے پاس تین سو دینار (اشرفیاں) بھیجے اور عرض کیا کہ ان کو اپنی ضروریات میں صرف کرلیں۔ حضرت ابو ذرؓ نے واپس فرما دیے اور یہ فرما دیا کہ دنیا میں اللہ کے ساتھ دھوکہ کھانے والا میرے سوا کوئی نہ ملا؟ (یعنی دنیا کی اتنی بڑی مقدار اپنے پاس رکھنا اللہ تعالیٰ شا نہٗ سے غافل ہوناہے) اور یہی اللہ کے ساتھ دھوکہ ہے کہ اس کے عذاب سے آدمی بے فکر ہو جائے جس کو حق تعالیٰ شا نہٗ نے متعدد جگہ قرآنِ پاک میں ارشاد فرمایا کہ تم کو دھوکہ باز شیطان اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ میںنہ ڈال دے، جیسا کہ چھٹی فصل میں دنیا اور آخرت کی آیات میں نمبر (۳۸) پر آرہا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوذرؓ نے فرمایا کہ مجھے صرف تھوڑا سا سایہ چاہیے جس میں اپنے کو چھپالوں اور تین بکریاں جن کے دودھ پر ہم سب گزر کرلیں اور ایک باندی جو اپنی خدمت کا احسان ہم پر کردے۔ اس سے زائدجو ہو مجھے ان کے اندر اللہ سے ڈرلگتا ہے۔ ان کا یہ بھی ارشاد ہے کہ قیامت کے دن دو دِرَم والا ایک دِرَم والے کی بہ نسبت زیادہ قید میں ہوگا۔ (دُرِّمنثور)
حضرت عبداللہ بن صامتؓ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت ابوذر غفاری ؓ کے پاس تھا کہ ا ن کا روزینہ بیت المال سے آیا۔ ایک باندی ان کے پاس تھی جو ان میں سے ضروری چیزیں خرید کرلائی۔ اس کے بعد سات دِرَم ا ن کے پاس بچے۔ فرمانے لگے کہ اس کے پیسے کر لائو۔ (تاکہ تقسیم کر دیں) میں نے کہا: ان کوا پنے پاس رہنے دو کوئی ضرورت پیش آجائے، کوئی مہمان آجائے۔ فرمایا: مجھ سے میرے محبوب (ﷺ) نے یہ طے شدہ بات فرمائی تھی کہ جس سونے یا چاندی کو باندھ کر رکھاجائے گا وہ اپنے مالک پر آگ کی چنگاری ہے جب تک کہ اس کو اللہ کے راستہ میں خرچ نہ کر دیا جائے۔ (الترغیب و الترہیب)
حضرت شداد ؒ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوذرؓ حضورِ اقدسﷺ سے کوئی سخت حکم سنتے تھے پھر جنگل چلے جاتے تھے۔ (کہ اکثر جنگل میں قیام رہتا تھا) ان کے تشریف لے جانے کے بعد اس حکم میں کچھ سہولت پیدا ہو جاتی، جس کا ان کو علم نہ ہوتا۔ اس لیے وہ سخت ہی حکم پر قائم رہتے۔ (دُرِّمنثور)
یہ صحیح ہے کہ حضرت ابوذرؓ کا مسلک اس بارے میں بہت ہی سخت اور شدت کا ہے۔ باقی اس میں تو شک نہیں کہ زُہد کا کمال یہی ہے کہ جو ان کامسلک تھا اور بہت سے اکابر کا یہی پسندیدہ معمول رہا، مگرا س پر نہ تو کسی کو مجبور کیا جاسکتا ہے ، نہ اس پر عمل نہ کرنے میں جہنمی قرار دیا جاسکتا ہے۔ اپنی خوشی اور رضا و رغبت سے اختیار کرنے کی چیز یہی ہے۔ جس خوش نصیب کوبھی اللہ اپنے لطف و کرم سے نصیب فرمادے۔ کاش! اس دنیا کے کتّے کو بھی اللہ ان حضرات زاہدین کے اوصاف ِجمیلہ کا کچھ حصہ عطا فرما دیتا۔ فَإِنَّ اللّٰہَ عَلٰی کُلِّ شَیْئٍ قَدِیْرٌ۔
۶۔ وَمَا مَنَعَھُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْھُمْ نَفَقٰـتُھُمْ اِلاَّ اَنَّھُمْ کَفَرُوْا بِاللّٰہِ
اور ان منافقوں کی خیر خیرات قبول ہونے سے اس کے سوا کوئی چیز مانع نہیں ہے کہ انھوں نے
وَبِرَسُوْلِہٖ وَلَا یَاْتُوْنَ الصَّلٰوۃَ اِلاَّ وَھُمْ کُسَالٰی وَلَا یُنْفِقُوْنَ اِلاَّ وَھُمْ کرِھُوْنَ o فَلاَ تُعْجِبْکَ اَمْوَالُھُمْ وَلَا اَوْلاَدُھُمْ ط اِنَّمَا یُرِیْدُ اللّٰہُ لِیُعَذِّبَھُمْ بِھَا فِی الْحَیٰوۃِ الدُّنْیاَ وَ تَزْھََقَ اَنْفُسُھُمْ وَھُمْ کفِرُوْنَ o
(التوبۃ :ع ۷)
اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا (نفاق سے، اپنے کومؤمن بتاتے ہیں) یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے مگر بہت کاہلی سے (ہارے دل سے) اور نیک کاموں میں خرچ نہیں کرتے مگر ناگواری کے ساتھ۔ (بدنامی سے بچنے کی وجہ سے) ان (مردودوں) کا مال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالے، (کہ ایسے مردودوں پر
اتنے انعامات کیوں ہیں)اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے ان کو دُنیوی عذاب میں مبتلا رکھے (کہ ہر وقت ان کے فکروں میں مبتلا رہیں) اور کفر ہی کی حالت میں ان کی جان نکل جائے۔
فائدہ: ابتدا میں خیرات کے قبول ہونے میں کفر کے علاوہ کاہلی سے نماز پڑھنے کو اور بددلی سے صدقہ دینے کو بھی دخل بتایا ہے۔ نماز کے متعلق مضامین اس ناکارہ کے رسالہ ’’فضائلِ نماز‘‘ میں گزرچکے ہیں۔ اس میں حضورِ اقدسﷺ کایہ ارشاد گزرا ہے کہ اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں جس کی نماز نہیں۔ اس کے لیے دین نہیں جس کی نماز نہیں۔ نماز دین کے لیے ایسی ضروری چیز ہے جیسا کہ آدمی کے لیے اس کا سر ضروری ہے۔ حضورﷺ کا ارشاد ہے کہ جو نماز کو خشوع و خضوع سے اچھی طرح پڑھے وہ نما ز نہایت روشن چمک دار بن کر دعائے خیر دیتی ہوئی جاتی ہے اور جوبری طرح پڑھے وہ بری صورت میں سیاہ رنگ میں بددعا دیتی ہوئی جاتی ہے کہ اللہ تجھے بھی ایسا ہی برباد کرے جیسا تونے مجھے برباد کیا، اور ایسی نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر ماردی جاتی ہے۔ ایک حدیث میں حضورﷺ کا ارشاد واردہوا ہے کہ قیامت کے دن سب سے اوّل نماز کا حساب ہوگا، اگر وہ اچھی ہوئی تو باقی اعمال بھی اچھے ہوں گے، وہ بری ہوئی تو باقی اعمال بھی برے ہوں گے۔ دوسری حدیث میں ہے اگر وہ قبول ہوئی تو باقی اعمال بھی قبول ہوں گے، وہ مردود ہوگئی تو باقی اعمال بھی مردود ہوں گے۔ (فضائلِ نماز)
اس کے بعد آیتِ شریفہ میں بددلی سے صدقہ کا ذکر فرمایا ہے۔ اور بددلی سے صدقہ دینا ظاہر ہے کہ کیا قابل قبول ہوسکتا ہے؟ لیکن اگر وہ صدقہ فرض ہے جیسا کہ زکوٰۃ، تو وجوب ساقط ہو ہی جائے گا۔ اسی واسطے حضورِ اقدس ﷺ نے زکوٰۃ ادا کرنے کی روایات میں متعدد جگہ طَیِّبَۃً بِھَا نَفْسُہُ۔ (الترغیب والترہیب) رَافِدَۃً عَلَیْہِ کُلَّ عَامٍ۔ (ابوداؤد) وغیرہ الفاظ ذکر فرمائے جن کا مطلب یہی ہے کہ نہایت خوش دلی سے ادا کرے، تاکہ فرض ادا ہونے کے علاوہ اس کااجر و ثواب بھی ہو اور اس پر اِنعام واِکرام بھی ہو۔ ’’ابوداود شریف‘‘ کی ایک روایت میں حضورﷺ کا ارشاد ہے کہ جو شخص ثواب کی نیت سے ادا کرے گا اس کو اس کا اجر ملے گا اور جو ادا نہ کرے گا ہم اس کو لے کر رہیں گے۔ اور بعض روایات میںاس کے ساتھ تاوان بھی وارد ہے کہ ادا نہ کرنے کی صورت میں جرمانہ بھی کریںگے۔
حضرت جعفر بن محمد ؒ کہتے ہیں کہ وہ امیر المؤمنین ابوجعفر منصور ؒ کے پاس گئے تو وہاں حضرت زبیرؓ کی اولاد میں سے کوئی شخص تھے جنہوں نے منصور سے اپنی کوئی حاجت پیش کی تھی اور منصور نے ان کی درخواست پرکچھ ان کودینے کا حکم بھی کر دیاتھا، مگر وہ مقدار زبیری کے نزدیک کم تھی، جس کی شکایت انھوںنے کی اور منصور کو اس پر غصہ آگیا۔ حضرت جعفر ؒ نے فرمایا کہ مجھے اپنے باپ دادوں کے واسطے سے حضورﷺ کایہ ارشاد پہنچا ہے کہ جو عطا خوش دلی سے دی جائے اس میں دینے والے کے لیے بھی برکت ہوتی ہے اور لینے والے کے لیے بھی۔ منصور نے یہ حدیث سنتے ہی کہا: خدا کی قسم! دیتے وقت تو مجھے خوش دلی نہ تھی مگر تمہاری حدیث سن کر مجھ میں طیبِ نفس پیدا ہوگیا۔ اس کے بعد حضرت جعفر ؒ ان زبیری کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے فرمایا کہ مجھے اپنے باپ دادوں کے ذریعہ سے حضورﷺ کا یہ ارشاد پہنچا ہے کہ جو شخص قلیل رزق کو کم سمجھے اللہ اس کو کثیر سے محروم فرما دیتے ہیں۔ زبیری کہنے لگے کہ خدا کی قسم! پہلے سے تو یہ عطیہ میری نگاہ میں کم تھا، تمہاری حدیث سننے کے بعد بہت معلوم ہونے لگا۔ سفیان بن عیینہ ؒ جو اس قصہ کو نقل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے زبیری سے پوچھا کہ وہ کیا مقدار تھی جو تمہیں منصور نے دی تھی؟ وہ کہنے لگے کہ اس وقت تو بہت تھوڑی سی تھی، لیکن میرے پاس پہنچنے کے بعد اللہ نے اس میں ایسی برکت اور نفع عطا فرمایا کہ وہ پچاس ہزار کی مقدار تک پہنچ گئی۔ سفیان ؒ کہتے ہیں کہ یہ لوگ (اہلِ بیت حضرت جعفر ؒ اور ان کے اَکابر کی طرف اشارہ ہے) بھی بارش کی طرح جہاں پہنچ جاتے ہیں نفع ہی پہنچاتے ہیں۔ (کنز العمال)
مطلب یہ ہے کہ اس جگہ دو حدیثیں سنا کر دونوں کوخوش اور مطمئن کر دیا۔ اس طرح سے یہ حضرات جہاں بھی پہنچتے ہیں روحانی یا مادّی نفع پہنائے بغیر نہیں رہتے۔ اس کے ساتھ ہی اُس زمانہ کے اُمرا کی یہ چیز بھی قابلِ رشک ہے کہ بادشاہت کے باوجود حضورﷺ کے ارشادات سن کر ان کے سامنے گردن رکھ دینا اس زمانہ کی عام فضا تھی۔
آیتِ شریفہ میں اس کے بعد آل، اولاد اور مال کو دنیا میں عذاب کا ذریعہ فرمایا۔ ان چیزوں کا دنیا میں موجبِ دِقّت اور کلفت ہونا ظاہر ہے۔ کہیں اولاد کی بیماری ہے، کہیں ان پر مصائب ہیں، کہیں ان کے مرنے کا رنج و حسرت ہے۔ اور یہ سب چیزیں مسلمانوں پر بھی پیش آتی ہیں، لیکن مسلمان کے لیے چوںکہ ہر تکلیف جو دنیا میں پیش آئے وہ آخرت میں اجرو ثواب کا ذریعہ ہے، اس لیے وہ تکلیف نہیں رہتی، کیوںکہ وہ تکلیف تکلیف نہیں بلکہ راحت ہے جس کے بدلہ میں کہیں اس سے زیادہ مل جائے۔ اور جن کے لیے آخرت میں ان مصائب کا بدلہ نہیں ہے ان کے لیے یہ دنیا کا عذاب ہی عذاب رہ گیا۔ ابنِ زید ؒ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کے دنیا میں عذاب ہونے سے مصائب مراد ہیں کہ ان کے لیے یہ عذاب ہیں اور مؤمنین کے لیے ثواب کی چیزیں ہیں۔
۷۔ وَلَا تَجْعَلْ یَدَکَ مَغْلُوْلَۃً اِلٰی عُنُقِکَ وَلَا تَبْسُطْھَا کُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا o اِنَّ رَبَّکَ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَّشَآئُ وَیَقْدِرْط اِنَّہٗ کَانَ بِعِبَادِہٖ خَبِیْرًا م بَصِیْرًا o
(بني إسرائیل : ع ۳)
اور نہ تو (بخل کی وجہ سے) اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے باندھ لینا چاہیے اور نہ بہت زیادہ کھول دینا چاہیے (کہ اِسراف کی حد تک پہنچ جائے کہ اس صورت میں) ملامت زدہ اور (فقر کی وجہ سے) تھکے ہوئے بیٹھے رہو۔ (اور محض کسی کے فقر کی وجہ سے
اپنے کو پریشانی میںمبتلا کرنا مناسب نہیں) بے شک تیرا ربّ جس کو چاہتا ہے زیادہ رزق دیتا ہے اور جس پرچاہتا ہے تنگی کرتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں (کی مصالح اور ان کے اَحوال) سے باخبر ہے (کہ کس کے لیے کتنا مناسب ہے اور ان کے اَحوال کو) دیکھنے والا ہے۔
فائدہ: قرآنِ پاک میں اس جگہ معاشرت کے بہت سے آداب پر بڑی تفصیلی تنبیہات فرمائی ہیں۔ من جملہ ان کے اس آیتِ شریفہ میں بخل اور اِسراف پر تنبیہ فرماکر اعتدال اور میانہ روی کی گویا ترغیب دی۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ حضورِ اقدس ﷺ سے کسی نے کچھ سوال کیا، حضورﷺ نے ارشاد فرمایاکہ اس وقت تو کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اپناکرتہ جو آپ پہن رہے ہیں یہ دے دیجیے۔ حضورﷺ نے کرتہ نکال کر مرحمت فرما دیا۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔ حضرت ابنِ عباس? فرماتے ہیں کہ یہ آیتِ شریفہ خانگی اِخراجات کے بارہ میں ہے کہ نہ ان میں زیادہ بخل کیا جائے اور نہ بہت وسعت اِختیار کی جائے، میانہ روی اِختیار کی جائے۔ حضورِ اقدسﷺ سے بھی متعدد روایات میں یہ مضمون ذکرکیا گیا کہ جو شخص میانہ روی اِختیار کرے وہ فقیر نہیں ہوتا۔ اور آیتِ شریفہ کے ختم پر اس اَحمقانہ خیال کی تردید فرمائی کہ سب کے سب مالی حیثیت سے برابری کا درجہ رکھتے ہیں، یہ صرف اللہ کے قبضۂ قدرت میں ہے کہ وہ جس پر چاہے فراخی فرمائے جس پر چاہے تنگی کرے۔ وہی بندوں کے اَحوال سے واقف ہے، وہی ان کی مصالح کوخوب جانتا ہے۔
حضرت حسن ؒ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ شا نہٗ بندوں کے اَحوال سے باخبر ہیں۔ جس کے لیے ثروت بہتر سمجھتے ہیں اس کو ثروت عطا فرماتے ہیں اور جس کے لیے تنگی مفید سمجھتے ہیں اس پر تنگی فرماتے ہیں۔ دوسری جگہ قرآن پاک میں ارشاد ہے:
{وَلَوْ بَسَطَ اللّٰہُ الرِّزْقَ لِعِبَادِہٖ لَبَغَوْا فِی الْاَرْضِ وَلٰکِنْ یُّنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّایَشَآئُ ط اِنَّہٗ بِعِبَادِہٖ خَبِیْرٌ م بَصِیْرٌ o}
(الشوری : ع ۳)
اگر اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کے لیے روزی میں وسعت کر دیتا تو وہ دنیا میں شرارت (اور فساد) کرنے لگتے، لیکن حق تعالیٰ شانہٗ (جس کے لیے) جتنا رزق
مناسب سمجھتا ہے اُتارتا ہے۔ وہ اپنے بندوں (کی مصالح) سے باخبر، (اور ان کے اَحوال کو) دیکھنے والا ہے۔
فائدہ: اس آیتِ شریفہ میںاس طرف اشارہ ہے کہ سب پر وسعت کاہونا دنیا میں سرکشی اور فساد کاسبب ہے۔ اور قرینِ قیاس اور تجربہ کی بات بھی ہے کہ اگر حق تعالیٰ شا نہٗ اپنے لطف سے سب ہی کو مال دار بنا دیں تو پھر دنیا کا نظام چلنا ناممکن ہو جائے کہ سب تو آقا بن جائیں مزدوری کون کرے۔ ابنِ زید ؒ کہتے ہیں کہ عرب میںجس سال پیداوار کی کثرت ہوتی ایک دوسرے کو قید کرنا اور قتل کرنا شروع کر دیتے، اور جب قحط پڑجاتا تو اس کو چھوڑ دیتے۔ (دُرِّمنثور)
حضرت علی ؓ اور متعدد حضرات صحابہ کرامcسے نقل کیا گیا کہ اَصحابِ صُفَّہ نے دنیا کی تمناکی تھی جس پر آیتِ شریفہ {وَلَوْ بَسَطَ اللّٰہُ الرِّزْقَ } نازل ہوئی۔ حضرت قتادہ ؒ اس آیتِ شریفہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بہترین رزق وہ ہے جو نہ تجھ میں سرکشی پیدا کرے، نہ اپنے اندر تجھے مشغول کرلے ہمیں یہ بتایا گیا کہ ایک مرتبہ حضورِ اقدسﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ دنیا کی چمک دمک ہے۔ کسی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا خیر (مال)بھی برائی کا سبب بن جاتا ہے؟ اس پر یہ آیتِ شریفہ {وَلَوْ بَسَطَ اللّٰہُ الرِّزْقَ} نازل ہوئی۔
حضورِاقدسﷺ سے حدیثِ قدسی میں اللہ کا پاک ارشاد نقل کیا گیا کہ جو شخص میرے کسی ولی کی اِہانت کرتا ہے وہ میرے ساتھ لڑائی کے لیے مقابلہ میںآتا ہے۔ میںاپنے دوستوں کی حمایت میں ایسا غصہ میں آتا ہوں جیسا کہ غضب ناک شیر۔ اور کوئی بندہ میرے ساتھ تقرب ان چیزوں سے زیادہ کسی چیز سے حاصل نہیں کرسکتا جو میں نے ان پر فرض کی ہیں۔ (یعنی حق تعالیٰ شا نہٗ نے جو چیزیں فرض کر دیں ان کی بجا آوری سے جتنا تقرب حاصل ہوتا ہے کسی چیز سے حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد دوسرے درجہ میں نوافل کے ذریعہ تقرب حاصل ہوتا ہے) اور نوافل کے ذریعہ سے بندہ میرے ساتھ قرب حاصل کرتا رہتا ہے (اور جتنا نوافل میںاِضافہ ہوتا رہے گااتنا ہی قرب میںاِضافہ ہوتا رہے گا) یہاں تک کہ وہ میرا محبوب بن جاتا ہے تو میںاس کی آنکھ ،کان ، ہاتھ اور مددگار بن جاتا ہوں۔ اگر وہ مجھے پکارتاہے تو میںاس کی پکار کو قبول کرتا ہوں اور مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو اس کا سوال پورا کرتاہوں، اور مجھے کسی چیز میں جس کے کرنے کا میں ارادہ کرتا ہوں اتنا تردّد نہیں ہوتا جتنا اپنے مؤمن بندہ کی روح قبض کرنے میں تردّد ہوتا ہے کہ وہ (کسی وجہ سے) موت کو پسند نہیں کرتا اور میںاس کا جی برا کرنا نہیں چاہتا، لیکن موت ضروری چیز ہے۔ میرے بعض بندے ایسے ہیں کہ وہ کسی خاص نوع کی عبادت کے خواہش مند ہوتے ہیں، لیکن میں اس لیے وہ نوع عبادت کی ان کو میسر نہیں کرتا کہ اس سے اُن میں عُجب پیدا نہ ہو جائے۔ میرے بعض بندے ایسے ہیں جن کے ایمان کو ان کی تندرستی ہی درست رکھ سکتی ہے۔ اگر میں ان کوبیمار کر دوں تو ان کی حالت خراب ہو جائے۔ اور بعض بندے ایسے ہیں جن کے ایمان کو ان کی بیماری ہی درست رکھ سکتی ہے۔ اگر میں ان کو تندرستی دے دوں تو وہ بگڑ جائیں۔ میںاپنے بندوں کے حال کے موافق عمل درآمد کرتاہوں، اس لیے کہ میں ان کے دلوں کے اَحوال سے واقف ہوں اور باخبر ہوں ۔(دُرِّمنثور)
یہ حدیث شریف بڑی قابلِ غور ہے، اس کا تعلق تکوینی اُمور سے ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی غریب ہے تو اس کی اِمداد کی ہمیں ضرورت نہیں، کوئی بیمار ہے تو اس کے علاج کی ضرورت نہیں۔ اگر یہ ہوتا تو پھر صدقات کی سب روایات اور آیات بے محل ہو جاتیں۔ دوا کرنے کا حکم جن روایات میں ہے وہ بے محل ہوتیں۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ تکوینی طور پر یہ سلسلہ تو اسی طرح رہے گا، کوئی ماہر ڈاکٹر یا محکمۂ حفظانِ صحت یہ چاہے کہ کوئی بیمار نہ ہو، ناممکن کوئی حکومت یہ کوشش کرے کہ کوئی غریب نہ رہے، کبھی نہیں ہوسکتا۔ البتہ ہم لوگ اپنی وسعت کے موافق ان کی اِعانت کے، ہمدردی کے ، علاج کے، اِمداد کے مامور ہیں۔ اور جتنی کوئی شخص اس میں کوشش کرے گا اس کا اجر ، اس کا ثواب ، اس کا دین اور دنیا میں اس کو بدلہ ملے گا۔
لیکن اپنی سعی کے باوجود کوئی بیمار اچھا نہیں ہوتا، اپنی کوشش کے باوجود کسی کی مالی حالت درست نہیں ہوتی، تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی میں میرے لیے خیر ہے۔ اس سے پریشان اورگھبرانا نہیں چاہیے۔ اور چوںکہ غیب کی خبر نہیں اور تکوینی چیزوں پر عمل کے ہم مامور نہیں، اس لیے اپنی کوشش علاج اوراِعانت و ہمدردی اور مدد زیادہ سے زیادہ رکھنی چاہیے۔
وَاللّٰہُ الْمُوَفِّق لِمَا یُحِبُّ وَیَرْضَی
۸۔ وَابْتَغ فِیْمَآ اٰتٰکَ اللّٰہُ الدَّارَ الْاٰخِرَۃَ وَلَا تَنْسَ نَصِیْبَکَ مِنَ الدُّنْیَا وَاَحْسِنْ کَمَا اَحْسَنَ اللّٰہُ اِلَیْکَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِی الْاَرْضِط اِنَّ اللّٰہَ لاَ یُحِبُّ الْمُفْسِدِیْنَ o (القصص: ع ۸)
اور تجھے جو کچھ اللہ نے دے رکھا ہے اس میں عالمِ آخرت کی بھی جستجو کر اور دنیا سے اپنا حصہ (آخرت میں لے جانا) فراموش نہ کر، جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا تو بھی (بندوں پر)
احسان کر، (اور خدا کی نافرمانی اور حقوق کو ضائع کرکے) دنیا میں فساد نہ کر۔ بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسندنہیں کرتا۔
فائدہ: یہ قرآنِ پاک میں مسلمانوںکی طرف سے قارون کو نصیحت کا بیان ہے۔ اس کا پورا قصہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے بیان میں پانچویں فصل کی آیات کے سلسلہ میں نمبر(۳) پر آرہا ہے۔ سدی ؒ کہتے ہیں کہ ’’آخرت کی جستجو کرنے‘‘ کامطلب یہ ہے کہ اللہ کاتقرب حاصل کر اور صلہ رحمی کر۔ حضرت ابنِ عباس? فرماتے ہیں کہ’’ دنیا سے اپنا حصہ مت بھول‘‘ کامطلب یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرنا نہ چھوڑ۔ مجاہد ؒکہتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یہ دنیا سے اپنا حصہ ہے جس کا ثواب آخرت میں ملتا ہے۔ حسن بصری ؒ فرماتے ہیں کہ بقدرِ ضرورت اپنے لیے روک کر باقی زائد کا خرچ کر دینا اور آگے چلتا کر دینا یہ دنیا میں سے اپنا حصہ ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک سال کا خرچ روک کر باقی کا صدقہ کر د ے۔ (دُرِّمنثور)
آدمی کا اپنی دنیا میں سے اپنی آخرت کا حصہ بھلا دینا اپنے نفس پراِنتہائی ظلم ہے۔ حضورِ اقدس ﷺ کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن آدمی ایسی حالت میں اللہ کے سامنے لایا جائے گا جیسا کہ (ضعف اور ذلت کے اعتبار سے) بھیڑکا بچہ ہو۔ حق تعالیٰ شا نہٗ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ وہاں سے مطالبہ ہوگا کہ میں نے تجھے مال دیا، دولت عطا کی، تجھ پر بڑے بڑے احسانات کیے، تو نے میرے انعامات میںکیا کارگزاری کی؟ وہ عرض کرے گا: یااللہ! میں نے مال خوب جمع کیا،اس کو خوب بڑھایا، اور جتنا مال تھا اس سے بہت زیادہ ا س کو کرکے دنیا میں چھوڑ آیا، آپ مجھے دنیا میں واپس کر دیں تو میں وہ سب کچھ اپنے ساتھ لے آئوں۔ارشاد ہوگا: وہ دکھاؤ جس کو ذخیرہ بنا کر آگے بھیج رکھا ہو۔ وہ پھوپھی عرض کرے گا کہ یا اللہ! میں نے اس کو بہت ہی جمع کیا اور بڑھایا، اور جتنا تھا اس سے بہت زیادہ کرکے چھوڑ آیا۔ مجھے آپ واپس بھیج دیں میں وہ سارا ہی ساتھ لے آؤں بالآخر جب اس کے پاس ذخیرہ ایسانہ ہوگا جس کو آگے بھیج رکھا ہو تو اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ (مشکاۃ المصابیح) یہ اللہ اور اس کے پاک رسولﷺ کے ارشادات بڑے غور اوربہت اہتمام سے عمل کرنے کی چیزیں ہیں۔ سرسری پڑھ کر چھوڑ دینے کے واسطے نہیں ہیں۔ دنیاکی زندگی کو جو بالکل خواب کی مثال ہے بہت اہتمام سے آخرت کی تیاری کے لیے غنیمت سمجھو اور جوکمایا جاسکے کمالو۔ حق تعالیٰ شا نہٗ مجھے بھی توفیق عطافرمائے۔
۹۔ ھٰٓاَنْتُمْ ھٰؤُلَآئِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰہِ ج فَمِنْکُمْ مَنْ یَّبْخَلُ ج وَمَنْ یَبْخَلْ فَاِنَّمَا یَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِہٖ ج وَاللّٰہُ الْغَنِیُّ وَاَنْتُمْ الْفُقَرَآئُ ج وَاِنْ تَتَوَلَّوْا یَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَیْرَکُمْ ثُمَّ لَایَکُوْنُوْا اَمْثَالَکُمْ o (محمد:ع ۴)
تم لوگ ایسے ہو کہ تم کو اللہ کی راہ میں (تھوڑا سا) خرچ کرنے کوبلایا جاتا ہے سو اس پربھی تم میں سے بعض آدمی بخل کرنے لگتے ہیں۔ (اگر زیادہ مانگا جاتاتو کیا کرتے؟) اور جو شخص بخل کرتا ہے وہ خود اپنے ہی سے بخل کرتا ہے۔ (اس لیے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا
نفع اسی کو ملتا) اللہ تعالیٰ تو غنی ہے (اس کو تمہارے مال کی پرواہ نہیں) اورتم محتاج ہو (دنیا میں بھی اور آخرت میںبھی، اور اسی لیے تمہیں صدقہ کا حکم دیاجاتا ہے کہ اس کا نفع تم ہی کو پہنچتا ہے) اور اگر تم (اللہ تعالیٰ کے اَحکام سے) روگردانی کرو گے، تو خدا تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوم پیداکر دے گا اور پھر وہ تم جیسے (روگردانی کرنے والے) نہ ہوں گے۔ (بلکہ نہایت فرماں بردار ہوں گے)
فائدہ: یہ ظاہر بات ہے کہ اللہ کی کوئی غرض ہماری خیرات اور صدقات کے ساتھ وابستہ نہیں ہے۔ اس نے جس قدر زیادہ ترغیبیں اپنے پاک کلام اوراپنے پاک رسولﷺ کے ذریعہ سے فرمائی ہیں وہ ہمارے ہی نفع کے واسطے ہیں۔ چناںچہ پہلی فصل میں بہت سے دینی اور دنیوی فوائد صدقہ کے گزرچکے ہیں۔ اور جب ایک حاکم، مالک، خالق کسی شخص کو ایسے کام کا حکم کرے جس سے حکم کرنے والے کا کوئی نفع نہ ہو، بلکہ جس کو حکم دیا ہے اسی کا نفع ہو اور پھر بھی وہ حکم عدولی کرے، تو یقیناً اس کا جتنا خمیازہ بھی بھگتے وہ ظاہر ہے۔
ایک حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ شا نہٗ بہت سے لوگوں کو نعمتیں اس لیے دیتا ہے کہ لوگوں کو نفع پہنچائیں۔ جب تک وہ لوگ ایسا کرتے ہیں وہ نعمتیں ان کے پاس رہتی ہیں۔ جب وہ اس سے روگردانی کرنے لگتے ہیںوہ نعمتیں ان سے چھین کرحق تعالیٰ شا نہٗ دوسروں کی طرف منتقل کر دیتے ہیں۔ (کنز العمال) اور یہ نعمتیں مال ہی کے ساتھ مخصوص نہیں۔ عزت، وجاہت، اثر وغیرہ سب ہی چیزیں اس میںداخل ہیں اور سب کا یہی حال ہے۔ بعض احادیث میں آیا ہے کہ جب یہ آیتِ شریفہ نازل ہوئی کہ اگر تم روگردانی کرو گے تو اللہ دوسری قوم کو پیدا کر دے گا تو بعض صحابہ ? نے پوچھا: حضور ! یہ لوگ کِن میں سے ہوں گے جو ہماری روگردانی کی صورت میں ہمارے بدل ہوں گے؟ تو حضورﷺ نے حضرت سلمان فارسیؓ کے مونڈھے پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا کہ یہ اور ان کی قوم۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے! کہ اگر دین ثریا (جو چند ستاروں کے مجموعہ کا نام ہے) پر ہوتا تو فارس کے کچھ لوگ وہیں سے دین کو پکڑتے۔ متعدد روایات میں یہ مضمون آیا ہے۔ (دُرِّمنثور)
یعنی حق تعالیٰ شا نہٗ نے ان کو دین کی اتنی پرواز عطا فرمائی ہے کہ دین اور علم کو اگر و ہ ثریا پرہوتا، وہاں سے بھی حاصل کرتے۔ ’’مشکوٰۃ شریف‘‘ میں یہ روایت ’’ترمذی شریف‘‘ سے نقل کی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں حضورﷺ کا ارشاد نقل کیا کہ حضورﷺ کے سامنے عجمی لوگوں کا ذکر کیاگیا تو حضورﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ان پر یا ان میں سے بعض پر تم سے یاتم میں سے بعض سے زیادہ اعتماد ہے۔ (مشکاۃ المصابیح)
اور یہ ظاہر ہے کہ عجم میں بعض بعض اَکابر ایسے اونچے درجے اور حالات کے پیداہوئے ہیں کہ صحابی ہونے کی فضیلت کوچھوڑ کر دوسرے اِعتبارات سے ان کے کمالات بہت اونچے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی ؓ کے بہت سے فضائل حدیث میں آئے ہیں اور آنے بھی چاہئیں کہ دینِ حق کی تلاش میں انھوں نے بہت سی تکلیفیں اٹھائیں، بہت سے ملکوں کی خاک چھانی۔ ان کی عمر بہت زیادہ ہوئی۔ ڈھائی سو سال میں تو کسی معتمد کا اختلاف ہی نہیں ہے۔ بعض نے ساڑھے تین سوسال بتائی ہے اور بعض نے اس سے بھی زیادہ۔ حتیٰ کہ بعض نے کہا ہے کہ انھوں نے حضر ت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ و السلام کا زمانہ پایا۔ اور حضورﷺ کے اور حضرت عیسیٰ ؑ کے زمانہ میں چھ سو سال کا فرق ہے۔ ان کو پہلی کتابوں سے حضورِ اقدسﷺ نبی ٔ آخر الزمان کے مبعوث ہونے کی خبر معلوم ہوئی۔ یہ حضورﷺ کی تلاش میں نکل پڑے، اور راہبوں سے اور اس زمانہ کے عالموں سے تحقیق کرتے رہے، اور وہ لوگ حضورﷺ کے عن قریب پیدا ہونے کی بشارت اور حضورﷺ کی علامات بتاتے رہے۔ یہ فارس کے شہزادوں میں تھے۔ اسی تلاش میں ملک در ملک تلاش کرتے پھرتے تھے۔ کسی نے ان کو قید کرکے اپنا غلام بناکر فروخت کر دیا۔ پھر یہ اسی طرح بکتے رہے۔
خود فرماتے ہیں ’’بخاری شریف‘‘ میں روایت ہے کہ مجھے دس آقائوں سے زیادہ نے خریدا اورفروخت کیا۔ آخر میں مدینہ منورہ کے ایک یہودی نے ان کو خریدا۔ اس وقت حضورﷺ ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے۔ ان کو اس کی خبر ہوئی۔ یہ حضورﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اورجو علامات ان کو بتائی گئی تھیں ان علامات کو جانچا اور امتحان کیا۔ اس کے بعد مسلمان ہوئے اور اپنے یہودی آقا سے فدیہ دے کر (جس کو مکاتب بننا کہتے ہیں)آزاد ہوئے۔
ایک حدیث میںہے حضورﷺ نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ شا نہٗ چار آدمیوں کو محبوب رکھتے ہیں جن میں سلمان ؓ بھی ہیں۔ (اِصابہ) اس کا یہ مطلب نہیں کہ اور کسی سے محبت نہیں، بلکہ یہ ہے کہ یہ چار محبوبوں میں ہیں۔ ایک اور حدیث میںہے حضورِ اقدسﷺ کاارشاد ہے کہ ہر نبی کے لیے حق تعالیٰ شا نہٗ نے سات نُجبا بنائے ہیں، (یعنی مخصوص جماعت برگزیدہ لوگوں کی جو اس نبی کے کام کی ظاہری اورباطنی نگرانی کرنے والے، اور مدد کرنے والے ہوں) لیکن میرے لیے حق تعالیٰ شا نہٗ نے چودہ نُجبا مقررفرمائے ہیں۔ کسی نے عرض کیا: وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا: میں1 (یعنی حضرت علی) اور میرے دونوںبیٹے (حضرت حسن، حضرت حسین) اور حضرت جعفر اور حضرت حمزہ، ابوبکر، عمر، مصعب بن عمیر، بلال، سلمان، عمار، عبد اللہ بن مسعود، ابوذر غفاری، مقدادc۔ (مشکاۃ المصابیح)
حالات کی تفصیل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دین کے کسی اہم امر میں ان حضرات کی خصوصیات ہیں۔ ’’بخاری شریف‘‘ میں ہے کہ جب سورۂ جمعہ کی آیت { وَاٰخَرِیْنَ مِنْھُمْ لَمَّا یَلْحَقُوْا بِھِمْ} نازل ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ کون لوگ ہیں؟ حضورﷺ نے سکوت فرمایا۔ صحابہ ?نے مکرر دریافت کیا، حتیٰ کہ تین دفعہ سوال کیا، تو حضور ﷺ نے حضرت سلمان فارسیؓ کے اوپر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اگر ایمان ثریا پر ہوتا تو ان میں سے بعض آدمی وہاں سے بھی لے آتے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اگر علم ثریا پرہوتا۔ دوسری حدیث میں ہے: اگر دین ثریا پر ہوتا تو فارس کے کچھ لوگ وہاں سے بھی لے آتے۔ (فتح الباری)
علامہ سُیُوطی ؒ جو خود محققین شافعیہ میں ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت امام ابو حنیفہ ؒ کے فضائل میں پیشین گوئی کے طور پر ایسی صحیح چیز ہے جس پر اعتماد کیاجاتا ہے۔ (مقدمۂ اَوجز المسالک)
۱۰۔ مَآاَصَابَ مِنْ مُّصِیْبَۃٍ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِیْ اَنْفُسِکُمْ اِلاَّ فِیْ کِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَھَاط اِنَّ ذٰلِکَ عَلَی اللّٰہِ یَسِیْرٌo لِّکَیْلَا تَاْسَوْا عَلٰی مَا فَاتَکُمْ وَ لَا تَفْرَحُوْا بِمَآ اٰتٰـکُمْ وَاللّٰہُ لاَ یُحِبُّ کُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرِِo
کوئی مصیبت نہ دنیا میں آتی ہے اور نہ خاص تمہاری جانوں میں مگر وہ (سب) ایک کتاب میں (یعنی لوحِ محفوظ میں) ان جانوں کے پیدا ہونے سے پہلے لکھی ہوئی ہے اور یہ بات (کہ وقوع سے اتنا پہلے لکھ دینا) اللہ تعالیٰ کے نزدیک آسان کام ہے۔
الَّذِیْنَ یَبْخَلُوْنَ وَیَاْمُُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ط وَمَنْ یَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰہَ ھُوَ الْغَنِیُّ الْحَمِیدُ o (الحدید : ع۳)
(اور یہ اس لیے بتلادیا) تاکہ جو چیز (عافیت، مال یا اولاد وغیرہ) تم سے جاتی رہے اس پر (زیادہ) رنج نہ کرو اور جو تم کو ملے اس پر
اِترائو نہیں (اس لیے کہ اتِراوے وہ جس کو اپنے اِستحقاق سے ملے اور جو دوسرے کے حکم سے ایک چیز ملے اس پرکیا اِترانا؟) اوراللہ تعالیٰ کسی اترانے والے شیخی باز کوپسند نہیں کرتا۔ (بالخصوص) جولوگ ایسے ہیں کہ خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی تعلیم کرتے ہیں، اور جو (اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے سے) یا دینی کاموں سے اِعراض کرے گا تو اللہ تعالیٰ (کا کیا نقصان کرے گا؟ وہ تو) بے نیاز ہے حمد کے لائق۔
فائدہ: مصائب پر رنج تو طبعی چیز ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اتنا زیادہ رنج نہ ہو کہ دین اور دنیا کے سب ہی کاموں سے روک دے۔ اور یہ بھی طبعی چیز ہے کہ جب کسی بات کے متعلق یہ پختہ یقین پہلے سے ہو جائے کہ فلاں بات ہو کر رہے گی، کسی سعی اور کوشش سے وہ ملتوی نہیں ہوسکتی، تو پھر اس پر رنج و غم ہلکا ہو جایا کرتاہے۔ برخلاف اس کے کہ کوئی بات خلافِ توقع پیش آئے، تو اس پر رنج زیادہ ہوا کرتا ہے۔ اس لیے اس آیتِ شریفہ میں اس پر متنبہ کر دیا کہ موت و حیات، رنج و خوشی، راحت و آفت، یہ سب چیزیں ہم نے پہلے سے طے کر رکھی ہیں، وہ اسی طرح ہو کر رہیں گی۔ پھر اس میں اِترانے یا غم سے ہلاکت کے قریب ہو جانے کی کیا بات ہے؟
آیتِ شریفہ میں دولفظ وارد ہوئے ہیں مُخْتَالٍ، فَخُوْرٍ۔ جس کا ترجمہ اِترانے والے شیخی باز کاکیا ہے۔ اِترانا اپنے آپ ہوتا ہے، یعنی دوسرے کے بغیر بھی ہوتا ہے۔ اور شیخی دوسرے کے سامنے اور دوسرے کے مقابلہ میں ہواکرتی ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اِختیال تو ایسی چیزوں پر اِترانا ہوتا ہے جو آدمی کے اندر ذاتی کمال ہوں اور فخر ایسی چیزوں پر ہوتا ہے جو خارجی ہوں جیسا مال جاہ وغیرہ۔ (بیان القرآن)
حضرت قَزعہ ؒکہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر? کو موٹے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا۔ میں نے عرض کیا کہ میں خراسان کے بنے ہوئے نرم کپڑے یہ لایا ہوں، اگر آپ ان کو پہن لیں تو آپ کے بدن پریہ کپڑے دیکھ کر میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ انھوںنے فرمایا: مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ کپڑے پہن کر کہیں میں ’’مختال فخور‘‘ نہ بن جائوں۔ (دُرِّمنثور) یعنی ان کے پہننے سے کہیں مجھ میں عُجب اورتفاخُر پیدا نہ ہونے لگے۔
۱۱۔ ھُمُ الَّذِیْنَ یَقُوْلُوْنَ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰی مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰہِ حَتّٰی یَنْفَضُّوْاط وَلِلّٰہِ خَزَآئِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلٰکِنَّ الْمُنٰفِقِیْنَ لَایَفْقَھُوْنَ o
(المنافقون : ع۲)
یہی (منافقین) وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ رسول اللہ(ﷺ) کے پاس جمع ہیں ان پرکچھ خرچ نہ کرو یہاں تک کہ یہ آپ ہی (خرچ نہ ملنے کی وجہ سے حضورِ اقدس ﷺ کے پاس سے) منتشر
ہو جائیں گے۔ اور (بے وقوف یہ نہیں جانتے کہ) اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں سب خزانے آسمانوں کے اور زمینوں کے، لیکن یہ منافق (اَحمق ہیں) سمجھتے نہیں ہیں۔
فائدہ: متعدد روایات میں یہ مضمون واردہوا ہے کہ عبداللہ بن اُبی رئیس المنافقین اور اس کی ذُرِّیات نے یہ کہا کہ یہ لوگ جو حضورِ اقدسﷺ کے پاس جمع ہیں ان کی اِعانت کرناچھوڑ دی جائے۔ یہ بھوک سے پریشان ہو کر خود بخودمنتشر ہو جائیںگے۔ اس پر یہ آیتِ شریفہ نازل ہوئی۔ اور بالکل حق ہے، روز مرہ کا مشاہدہ ہے۔ سینکڑوں مرتبہ اس کا تجربہ ہوا کہ جب بھی کسی دینی کام کرنے والوں کے متعلق عناد اور بدباطنیت سے لوگوں نے یا کسی خاص فرد نے اِعانت روکی اللہ نے اپنے لطف وکرم سے دوسرا دروازہ کھول دیا۔ یہ ہر شخص کو یقین کے ساتھ سمجھ لینا چاہیے کہ روزی اللہ نے اپنے اور صرف اپنے ہی قبضہ میں رکھی ہے۔ وہ کسی کے باپ کے بند کرنے سے بھی بند نہیں ہوتی۔ البتہ بند کرنے والے دین کی اِعانت سے ہاتھ روک کر آخرت میں اللہ کے یہاں جواب دینے کے لیے تیارہو جائیں۔ جہاں نہ تو جھوٹ چل سکتا ہے کہ ہماری یہ غرض تھی نہ کوئی بیرسٹر یا وکیل کام دے سکتا ہے۔ فرضی حیلے تراش کرکے اللہ کے اور دین کے کاموں سے پہلوتہی کرنے سے بجزاس کے کہ اپنی ہی عاقبت خراب کی جائے اور کوئی فائدہ نہیں۔ ذاتی عناد اور دنیوی اَغراضِ فاسدہ کی وجہ سے کسی دینی کام میں روڑے اٹکانا یاکسی دین کاکا م کرنے والے کی اِعانت سے ہاتھ روکنا یا دوسروں کوروکنا، اپنا ہی نقصان کرنا ہے کسی دوسرے کا نقصان نہیں۔
حضورِ اقدسﷺ کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی مدد سے ایسے وقت پہلوتہی کرے جب کہ اس کی آبرو گرائی جا رہی ہو، اس کا اِحترام توڑا جا رہا ہو، تو حق تعالیٰ شا نہٗ اس شخص کی مدد کرنے سے ایسے وقت میں بے اِلتفاتی فرماتے ہیں جب کہ یہ کسی مدد کرنے والے کی مدد کا خواہش مند ہو۔(مشکاۃ المصابیح)
حضورِ اقدسﷺ کاعمل امت کے لیے شاہراہ ہے۔ ہر چیز میںاس کی کوشش ہر امتی کا فرض ہے کہ حضورﷺ کا طریقہ کیا تھا۔ اور اس راہ پر چلنے کی حتیٰ الوسع کوشش کرنا چاہیے۔ حضور ﷺ کا معمول تھا کہ دشمنوں کی اِعانت سے بھی دریغ نہ تھا۔ سیکڑوں واقعات کتبِ احادیث و تاریخ میں اس پر شاہد ہیں۔ خود یہی عبداللہ بن اُبی منافقوں کاسردار جس قدر تکالیف اورا ذیتیں پہنچاسکتا تھا اس نے کبھی دریغ نہیں کیا۔ اسی شخص کا مقولہ اسی سفر کا جس میں آیت بالا نازل ہوئی یہ ہے کہ جب ہم لوگ مدینہ واپس پہنچ جائیں گے توعزت دارلوگ یعنی ہم لوگ ان ذلیلوں کو (یعنی مسلمانوں کو) مدینہ سے نکال دیںگے، لیکن ان سب حالات کے باوجو اسی سفر سے واپسی کے چند روزبعد یہ بیمار ہوا تو اپنے بیٹے سے جو بہت بڑے پکّے مسلمان تھے کہا کہ تم جاکر حضور ﷺ کو میرے پاس بلا لائو، تمہارے بلانے سے وہ ضرور آجائیں گے۔
یہ حضورﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اورباپ کی درخواست نقل کی، حضور ﷺ اسی وقت جوتے پہن کر ساتھ ہولیے۔ جب حضورﷺ کو اس نے دیکھا تورونے لگا۔ حضور ﷺ نے فرمایا: اے اللہ کے دشمن! کیاگھبرا گیا؟ اس نے کہا: میں نے اس وقت آپ کو تنبیہ کے واسطے نہیں بلایا، بلکہ اس واسطے بلایا کہ اس وقت مجھ پر رحم کریں۔ یہ کلمہ سن کر حضورِاقدسﷺ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور ارشاد فرمایا: کیا چاہتے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ میری موت کاوقت قریب ہے۔ جب میں مرجائوں تو میرے غسل دینے میں آپ موجود ہوںاور اپنے ملبوس میں مجھے کفن دیں اور میرے جنازہ کے ساتھ قبرتک جائیں اور میری نماز جنازِہ پڑھیں۔ حضور ﷺ نے ساری درخواستیں اس کی قبول فرمائیں، جس پر آیتِ شریفہ { وَلاََ تُصَلِّ عَلٰی اَحَدٍ مِّنْھُم } (البراء ۃ : ع ۱۱) نازل ہوئی۔ (دُرِّمنثور) جس میں حق تعالیٰ شانہٗ نے منافقین کے جنازہ کی نماز پڑھانے کی ممانعت فرمائی۔
یہ تھا حضورﷺ کا برتائو اپنے جانی دشمنوں کے ساتھ، اور یہ کرم تھا ان کمینوں کے ساتھ جو کسی وقت بھی سب و شتم اور عیب تراشی میں کمی نہ کرتے تھے۔ کیا ہم لوگ بھی اپنے دشمنوں کے ساتھ اس قسم کا کوئی معاملہ کرسکتے ہیں کہ اس جانی دشمن کی تکلیف کو دیکھ کر رحمۃللعالمین کی آنکھوں میں آنسو بھرآئے؟ اور جتنی فرمایشیں اس نے اپنے کفر کے باوجود کیں حضورﷺ نے اپنے کرم سے سب پوری کیں؟ اپنا کرتہ مبارک اتارکر اس کوکفن کے لیے مرحمت فرمایا اور بقیہ سب درخواستیں بھی پوری کیں، گو کفر کی وجہ سے اس کو کارآمد نہ ہوسکیں، بلکہ آیندہ کے لیے حق تعالیٰ شا نہٗ کی طرف سے اس انتہائی کرم کی ممانعت اتر آئی۔
۱۲۔ اِنَّا بَلَوْنٰھُمْ کَمَا بَلَوْنَآ اَصْحٰبَ الْجَنَّۃِ ج اِذْ اَقْسَمُوْا لَیَصْرِمُنَّھَا مُصْبِحِیْنَ o وَلَا یَسْتَثْنُوْنَ o فَطَافَ عَلَیْھَا طَائِفٌ مِّنْ رَّبِّکَ وَھُمْ نَآئِمُوْنَ o فَاَصْبَحَتْ کَالصَّرِیْمِ o فَتَنَادَوْا مُصْبِحِیْنَ o اَنِ اغْدُوْا عَلٰی حَرْثِکُمْ اِنْ کُنْتُمْ صَارِمِیْنَ o فَانْطَلَقُوْا وَھُمْ یَتَخَافَتُوْنَo اَنْ لاَّیَدْخُلَنَّھَا الْیَوْمَ عَلَیْکُمْ مِّسْکِیْنٌo وَّغَدَوْا عَلٰی حَرْد قَادِرِیْنَ o فَلَمَّا رَاَوْھَا قَالُوْا اِنَّا لَضَالُّوْنَ o بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ o قَالَ اَوْسَطُھُمْ اَلَمْ اَقُلْ لَّکُمْ لَوْلاٍَ
ہم نے (ان مکہ والوں کو سامانِ عیش دے کر) ان کی آزمایش کر رکھی ہے (کہ یہ ان نعمتوں میں کیا عمل کرتے ہیں؟) جیسا کہ (ان سے پہلے) ہم نے باغ والوں کی آزمایش کی تھی جب کہ ان باغ والوں نے آپس میں قسم کھائی اور عہد کیا کہ اس باغ کا پھل ضرور صبح کو جاکر توڑ لیں گے۔ اور (ان کو ایسا پختہ یقین تھا کہ) ان شاء اللہ بھی نہ کہا۔ پس اس باغ پر آپ کے ربّ کی طرف سے ایک عذاب پھر گیا (جوایک آگ تھی یا لُو) اور وہ لوگ سو رہے تھے۔ پس صبح کو وہ باغ ایسا رہ گیا جیسا کٹا ہوا
تُسَبِّحُوْنَ o قَالُوْا سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنَّا کُنَّا ظٰلِمِیْنَ o فَاَقْبَلَ بَعْضُھُمْ عَلٰی بَعْضٍ یَّتَلاَوَمُوْنَ o قَالُوْا یٰوَیْلَنَآ اِنَّا کُنَّا طٰغِیْنَ o عَسٰی رَبُّنَا اَنْ یُّبْدِلَنَا خَیْرًا مِّنْھَا اِنَّا اِلٰی رَبِّنَا رَاغِبُوْنَ o کَذٰلِکَ الْعَذَابُط وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَۃِ اَکْبَرُم لَوْ کَانُوْا یَعْلَمُوْنَ o
(القلم : ع ۱)
کھیت۔ (کہ خالی زمین رہ جاتی ہے اور بعض جگہ اس کو کاٹ کر اس جگہ آگ بھی لگا د ی جاتی ہے) پس صبح کو سویرے وہ باغ والے ایک دوسرے کو آوازیںدینے لگے کہ اگرپھل توڑنا ہے تو سویرے چلو۔ پس چلتے ہوئے آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے جا رہے تھے کہ آج کوئی محتاج تم تک نہ آنے پائے۔ وہ اپنے خیال میںاس
کے روک لینے پر اپنے آپ کو قادر سمجھ کر چلے۔ (کہ سب کچھ خود ہی لے آئیں گے) جب وہاں پہنچ کر اس کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم راستہ بھول گئے۔ (کہیں اور پہنچ گئے یہ تو وہ باغ نہیں ہے، لیکن جب قرائن سے معلوم ہوا کہ یہ وہی جگہ ہے تو کہنے لگے) کہ ہماری قسمت ہی پھوٹ گئی۔ ان میں جوایک آدمی (کسی قدر) نیک تھا (لیکن عمل میں ان کا شریکِ حال تھا) کہنے لگا کہ میں نے تم سے کہا نہ تھا (کہ ایسی بدنیتی نہ کرو غریبوں کو دینے سے برکت ہوتی ہے۔اب) اللہ کی پاکی کیوں نہیں بیان کرتے؟ (یعنی توبہ اِستغفار کرو) وہ باغ والے کہنے لگے: ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہم قصوروار ہیں۔ پھر ایک دوسرے کو اِلزام دینے لگے۔ (جیسا کہ عام طور سے عادت ہے کہ جب کوئی کام بگڑ جائے تو ہرایک دوسرے کو قصور وار بتایا کرتا ہے) پھر سب کے سب کہنے لگے کہ بے شک ہم سب ہی حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ (کسی ایک پر اِلزام نہیں ہے، سب کی یہی صَلاح تھی۔ سب مل کر توبہ کرو اس کی برکت سے) شاید ہمارا پروردگار ہم کو اس سے اچھا باغ دے دے، اب ہم توبہ کرتے ہیں۔ (اس کے بعد اللہ تنبیہ کے طور پر فرماتے ہیں کہ ) اسی طرح (دنیا کا) عذاب ہوا کرتا ہے (کہ ہم بدنیتی سے چیز ہی کو فناکر دیتے ہیں) اور آخر ت کا عذاب اس سے بھی بڑھ کر ہے، کیا اچھا ہوتا کہ یہ لوگ اس بات کو جان لیتے۔ (کہ غریبوں سے بخل کا نتیجہ اچھا نہیں)
فائدہ: یہ بڑی عبرت کا قصہ ہے جو ان آیات میںذ کرفرمایا ہے۔ جو لو گ غربا، مساکین، اہلِ ضرورت کو نہ دینے کے عہد پیمان کرتے ہیں، قسمیں کھاکھاکر وعدے کرتے ہیں کہ ان ضرورت مندوں کو ایک پیسہ بھی نہیں دیاجائے گا، ایک وقت روٹی بھی نہ دی جائے گی، یہ نالائق ہرگز اِعانت کے مستحق نہیں، ان کو دینا بے کار ہے، وہ اپنے سارے مال سے یوں بہ یک وقت ہاتھ دھو لیتے ہیں۔ اور جو نیک دل اس طرز کوپسند نہیں کرتے لیکن عملاً لحاظ ملاحظہ میں ان کے شریکِ حال ہو جاتے ہیں، وہ بھی عذاب کی بلا سے نجات نہیں پاتے۔
حضرت عبداللہ بن عباس? فرماتے ہیں کہ ان آیات میں جو واقعہ گزرا ہے وہ حبشہ کے رہنے والے آدمیو ں کا ہے۔ ان کے باپ کا ایک بہت بڑا باغ تھا۔ وہ اس میں سے مانگنے والوںکو بھی دیا کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوگیا تو اس کی اولاد کہنے لگی کہ ابا جان تو بے وقوف تھے، سب کچھ ان لوگوں پر بانٹ دیتے تھے۔ پھر قسمیں کھا کر کہنے لگے کہ ہم صبح ہی سارا باغ کاٹ لائیں گے اور کسی فقیر کو اس میں سے کچھ نہیں دیں گے۔ حضرت قتادہ ؒ کہتے ہیں کہ اس باغ کے مالک بڑ ے میاں کایہ دستور تھا کہ اس کی پیداوار میں سے اپنا ایک سال کا خرچ رکھ کہ باقی سب کاسب اللہ کے راستہ میں خرچ کر دیتے تھے۔ ان کی اولاد ان کو اس طرز سے روکتی رہتی تھی مگر وہ نہ مانتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی اولاد نے یہ کوشش کی جو اوپر ذکرکی گئی کہ ساراکا سارا روک لیں اور کسی غریب کو کچھ نہ دیں۔ سعید بن جبیر ؒکہتے ہیں کہ یہ باغ یمن میںتھا۔ اس جگہ کا نام ضروان تھا جو (یمن کے مشہور شہر) صنعا سے چھ میل تھا۔ ابنِ جریج ؒ کہتے ہیں کہ وہ عذاب جو اس باغ پر مسلط ہوا جہنم کی گھاٹی سے ایک آگ نکلی جو اس پر پھر گئی۔ مجاہد ؒکہتے ہیں کہ یہ باغ انگور کا تھا۔
حضرت عبداللہ بن مسعودؓ حضورِ اقدسﷺ کا پاک ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رہا کرو۔ آدمی بعض گناہ ایسے کرتا ہے کہ ا س کی نحوست سے علم کا ایک حصہ بھول جاتا ہے۔ (یعنی حافظہ خراب ہو جاتا ہے اور پڑھا ہوا بھول جاتا ہے) اوربعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے تہجد کو آنکھ نہیں کھلتی۔ اوربعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اس کی آمدنی جوبالکل اس کے لیے آنے کو تیارہوتی ہے، جاتی رہتی ہے۔ اس کے بعد حضورِ اقدسﷺ نے یہ آیتِ شریفہ تلاوت فرمائی { فَطَافَ عَلَیْھَا طَائِفٌ مِّنْ رَّبِّکَ} (الٓایۃ) اور فرمایا کہ یہ لوگ گناہ کی وجہ سے اپنے باغ کی پیداوار سے محروم ہوگئے۔ (دُرِّمنثور) خود حق تعالیٰ سبحانہ و تقدَّس کاقرآنِ پاک میں دوسری جگہ ارشاد ہے
{ وَمَا اَصَابَکُمْ مِّنْ مُّصِیْبَۃٍ فَبِمَا کَسَبَتْ اَیْدِیْکُمْ وَیَعْفُوْ عَنْ کَثِیْرٍط} (الشوری : ع ۱)
ا ور جو مصیبت تم کو پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی اعمال کی بدولت پہنچتی ہے اور (ہرگناہ پر نہیں پہنچتی، بلکہ) بہت سے گناہ تو حق تعالیٰ شا نہٗ معاف فرما دیتے ہیں۔
حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضورﷺ نے فرمایا کہ اس آیت کی تفسیر تمہیں بتائوں؟ اے علی! جوکچھ بھی تمہیں پہنچے، مرض ہو یا کسی قسم کا عذاب یا دنیا کی اورکوئی مصیبت ہو، وہ اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اس مضمون کو بندہ اپنے رسالہ ’’اِعتدال‘‘میں تفصیل سے لکھ چکا ہے وہاں دیکھاجائے۔
۱۳۔ وَاَمَّا مَنْ اُوْتِیَ کِتَابَہٗ بِشِمَالِہٖ فَیَقُوْلُ یٰلَیْتَنِیْ لَمْ اُوْتَ کِتٰبِیَہْ o وَلَمْ اَدْرِ مَا حِسَابِیَہْ o یٰلَیْتَھَا کَانَتِ الْقَاضِیَۃْ o مَا اَغْنٰی عَنِّیْ مَالِیَہْ o ھَلَکَ عَنِّی سُلْطَانِیَہْo خُذُوْہُ فَغُلُّوْہُo ثُمَّ الْجَحِیْمَ صَلُّوْہُ o ثُمَّ فِیْ سِلْسِلَۃٍ ذَرْعُھَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُکُوْہُ o اِنَّہٗ کَانَ لَایُؤْمِنُ بِاللّٰہِ الْعَظِیْمِ o وَلَا یَحُضُّ عَلٰی طَعَامِ الْمِسْکِیْنِ o فَلَیْسَ لَہُ الْیَوْمَ ھٰھُنَا حَمِیْمٌ o وَّلَا طَعَامٌ
اور جس شخص کا نامۂ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ (نہایت ہی حسرت سے) کہے گا: کیا اچھا ہوتا کہ مجھ کو میرا نامۂ اعمال ہی نہ ملتا۔ اور مجھ کو خبر ہی نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا ہے۔ کیا اچھا ہوتا کہ موت ہی سب قصہ ختم کر دیتی۔ (قیامت ہی نہ آتی جو حساب کتاب ہوتا ) میرا مال بھی میرے کچھ کام نہ آیا۔ میری جاہ (آبرو)بھی جاتی رہی۔ (اس کے لیے فرشتوں کو حکم ہوگا) اس کو پکڑو اورا س کوطوق
اِلاَّ مِنْ غِسْلِیْنٍ o لاَّیَاْکُلُہٗ اِلاَّ الْخَاطِئُوْنَ o (الحاقۃ : ع۱)
پہنا دو۔ پھر جہنم میں اس کو داخل کر دو۔ پھرایک ستّر گز لمبی زنجیر میںاس کو جکڑ دو۔
اس لیے کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ رکھتا تھا۔ (اور خود تو کیا کھلاتا) دوسرے آدمیوں کو بھی غریب کے کھلانے کی ترغیب نہ دیتا تھا۔ پس نہ تو آج اس کا کوئی یہاں دوست ہے۔ اور نہ اس کے لیے کوئی چیز کھانے کو ہے بجز غسلین کے۔ جس کو بجز بڑے گناہ گار وں کے اور کوئی نہ کھائے گا۔
فائدہ: ’’غسلین‘‘ کا مشہور ترجمہ دَھووَن کا ہے۔ یعنی زخموں وغیرہ کے دھونے سے جو پانی جمع ہو جائے وہ غسلین کہلاتا ہے۔ حضرت ابنِ عباس? سے نقل کیاگیا کہ زخموں کے اندر سے جو لہو پیپ وغیرہ نکلتی ہے وہ غسلین ہے۔ حضرت ابو سعید خدریؓ حضورِاقدسﷺ کا ارشادنقل کرتے ہیں کہ غسلین کا ایک ڈول اگر دنیا میں ڈال دیا جائے تو اس کی بدبو سے ساری دنیا سٹر جائے۔ نوف شامی ؒ سے نقل کیا گیا کہ وہ زنجیر جو سترگز لمبی ہے اس کا ہر گز سترباع ہے اور ہر باع اتنا لمبا ہے کہ مکہ مکرمہ سے کوفہ تک پہنچے۔ حضرت ابنِ عباس? سے اور دوسرے مفسرین سے نقل کیا گیا کہ یہ زنجیر پاخانہ کی جگہ کو داخل کرکے ناک میں کونکالی جائے گی اور پھر اس پر لپیٹ دی جائے گی جس سے وہ بالکل جکڑا جائے گا۔ (دُرِّمنثور)
اس آیتِ شریفہ میں مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینے پر بھی عتاب ہے۔ اس لیے آپس میں اپنے عزیزوں کو، اپنے اَحباب کو، ملنے والوں کو غربا پروری پر، مساکین کوکھلانے پلانے پر خاص طور سے ترغیب دیتے رہنا چاہیے کہ دوسروں کوترغیب دینے سے اپنے اندر سے بھی بخل کا مادہ کم ہوگا۔
۱۴۔ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
وَیْلٌ لِّکُلِّ ھُمَزَۃٍ لُّمَزَۃِ o نِالَّذِیْ جَمَعَ مَالاً وَّعَدَّدَہٗ o یَحْسَبُ اَنَّ مَالَہٗ اَخْلَدَہٗ o کَلَّا لَیُنْبَذَنَّ فِی الْحُطَمَۃِ o وَمَا اَدْرٰکَ مَا الْحُطَمَۃُ o
بڑی خرابی ہے ایسے شخص کے لیے جو پسِ پشت عیب نکالنے والا ہو ، منہ در منہ طعنہ دینے والا ہو۔ ما ل جمع کرکے رکھتا ہے اور (غایتِ محبت سے) اس کو بار بار گنتا ہے۔ وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا یہ مال اس کے
نَارُ اللّٰہِ الْمُوْقَدَۃُ الَّتِیْ تَطَّلِعُ عَلَی الْاَفْئِدَۃِ o اِنَّھَا عَلَیْھِمْ مُّؤْصَدَۃٌ o فِیْ عَمَدٍ مُمَدَّدَۃٍ o ( الہُمزۃ )
پاس ہمیشہ رہے گا۔ ہر گز نہیں، (یہ مال ہمیشہ نہیں رہے گا) خدا کی قسم! یہ شخص ایسی آگ میں ڈال دیا جائے گا کہ اس میں جو
چیز پڑجائے وہ آگ اس کو توڑ پھوڑ کر ڈال دے۔ آپ کو خبر بھی ہے وہ کیسی توڑ دینے والی آگ ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی آگ ہے جو دلوں تک پہنچ جائے گی۔ (یعنی دنیا کی آگ تو جہاں بدن میںلگی آدمی مر گیا، اور وہاں چوںکہ موت نہیں ہے اس لیے بدن میں لگتے ہی دل تک پہنچ جائے گی اور دل کی ذرا سی ٹھیس بھی آدمی کو بہت محسوس ہوتی ہے) اور وہ آگ ان لوگوں پر بند کر دی جائے گی اس طرح پرکہ وہ لوگ لمبے لمبے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔
فائدہ:
’’ ہُمَزَۃ لُمَزَۃ‘‘ کی تفسیر میں مختلف اقوال علماء کے ہیں۔ ایک تفسیر یہ بھی ہے جو اوپر نقل کی گئی ہے۔ حضرت ابنِ عباس ? او رمجاہد ؒ سے ہُمزہ کی تفسیر طعن دینے والا اورلُمزہ کی تفسیر غیبت کرنے والا نقل کی گئی ہے۔ ابنِ جریج ؒکہتے ہیں کہ ہُمزہ اشارہ سے ہوتا ہے آنکھ کے، منہ کے، ہاتھ کے، جس کے بھی اشارہ سے ہو، اور لُمزہ زبان سے ہوتا ہے۔
ایک مرتبہ حضورِ اقدسﷺ نے اپنی معراج کا حال بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں نے مردوں کی ایک جماعت دیکھی جن کے بدن قینچیوںسے کُترے جا رہے تھے۔ میں نے جبرئیل ؑ سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انھوں نے فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جو زینت اختیار کرتے تھے۔ (یعنی حرام کاری کے لیے بن سنور کر نکلتے تھے) پھر میں نے ایک کنواں دیکھا جس میں نہایت سخت بدبو آرہی تھی اور اس سے چلانے کی آوازیں آرہی تھیں۔ میں نے جبرئیل ؑ سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ انھوںنے بتایا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو (حرام کاری کے لیے) بنتی سنورتی تھیں اور ناجائز کام کرتی تھیں۔ پھر میں نے کچھ مرد اور عورتیں معلَّق دیکھیں جو پستانوں کے ذریعہ سے لٹک رہے تھے۔ میں پوچھا: یہ کون ہیں؟ تو جبرئیل ؑ نے بتایا کہ یہ طعن دینے، والے چغل خوری کرنے والے ہیں۔ (دُرِّمنثور)
اللہ اپنے فضل سے ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ اس سورتِ شریفہ میں بخل اور حرص کی خاص طور سے مذمت ارشاد فرمائی ہے کہ بخل کی وجہ سے مال جمع کرکے رکھتا ہے اور حرص کی وجہ سے بار بار گنتا ہے کہ کہیں کم نہ ہو جائے۔ اور اتنی محبت اس سے ہے کہ اس کے باربار گننے میں بھی مزہ آتاہے۔ اور یہ بری عادت تکبر اور تعلِّی کا سبب بنتی ہے، جس کی وجہ سے دوسروں کی عیب جوئی اور ان پر طعن و تشنیع پیداہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس سورت کے شروع میں ان عیوب پر تنبیہ فرمانے کے بعد اس بری خصلت کی مذمت ذکر کی ہے۔ اور ہر شخص اس خَبْط میں مبتلا ہے کہ مال کی اَفزایش اس کو آفات اورحوادث سے بچا سکتی ہے، گویا مال دارکو موت آتی ہی نہیں، اس لیے اس پر تنبیہ فرمائی گئی ہے۔ واقعات بھی کثرت سے اس کی تائیدکرتے ہیںکہ جب کوئی آفت اور مصیبت مسلط ہوتی ہے یہ مال و متاع سب رکھا رہ جاتا ہے، بلکہ مال کی کثرت بسا اوقات خود آفات کو کھینچتی ہے۔ کوئی زہر دینے کی فکر میں ہوتا ہے کوئی قتل کرنے کی۔ اور لوٹ مار، چوری ڈاکہ سینکڑوں آفات اس مال کی بدولت آدمی پر مسلط رہتی ہیں۔ اور جب مال زیادہ ہو جاتا ہے پھر تو عزیزو اَقارب، بیوی بیٹا سب ہی دل سے ا س کی خواہش کرنے لگتے ہیں کہ بڈھا کہیں مرے تویہ ہمارے ہاتھ آئے۔
۱۵۔ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اَرَاَیْتَ الَّذِیْ ُیکَذِّبُ بِالدِّیْنِ o فَذٰلِکَ الَّذِیْ یَدُعُّ الْیَتِیْمَ o وَلَا یَحُضُّ عَلٰی طَعَامِ الْمِسْکِیْنِ o فَوَیْلٌ لِّلْمُصَلِّیْنَ o الَّذِیْنَ ھُمْ عَنْ صَلَا تِھِمْ سَاھُوْنَ o الَّذِیْنَ ھُمْ یُرَآئُ وْنَ وَیَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ o (الماعون)
ًٔکیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ پس (اس شخص کا حال یہ ہے کہ) یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اور غریب کو (خود توکیا دیتا دوسروں کو بھی ان کے) کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ پس ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھتے ہیں (یعنی
نہیں پڑھتے اوراگر کبھی پڑھتے بھی ہیں تو) وہ لوگ دکھاوا کرتے ہیں اور ماعون کو روکتے ہیں۔ (بالکل دیتے ہی نہیں)
فائدہ: حضرت ابنِ عباس? فرماتے ہیں کہ یتیم کو دھکے دینا یہ ہے کہ اس کا حق روکتے ہیں۔ قتادہ ؒکہتے ہیں کہ اس کے دھکے دینے سے اس پر ظلم کرنا مراد ہے اور یہ چیز قیامت کے دن کو غلط سمجھنے سے پیدا ہوتی ہے۔ جس کو آخرت کے دن کا یقین ہوگا، وہاں کی جزا اورسزا کا پورا وثوق ہوگا، وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، اور اپنے مال کو جمع کرکے نہیں رکھے گا، بلکہ خوب خرچ کرے گا۔ اس لیے کہ جس کو اس کاکامل یقین ہوجائے کہ آج اگر میں اس تجارت میں دس روپے لگا دوں کل کو ضرور مجھے ایک ہزار جائز طریقے سے ملیں گے، وہ کبھی بھی اس میں تامُّل نہ کرے گا۔
اور جن نمازیوں کا اس میں ذکر ہے ان کے متعلق حضر ت ابنِ عباس? فرماتے ہیں کہ وہ منافق لوگ مراد ہیں جو لوگوں کے سامنے تو دکھلاوے کے واسطے نماز پڑھتے ہیں اور جہاں کہیں اکیلے ہوں اس کو چھوڑ دیں۔ حضرت سعدؓ وغیرہ متعدد حضرات سے نقل کیاگیاکہ نماز کو چھوڑنے سے مراد تاخیر سے پڑھنا ہے کہ بے وقت پڑھتے ہیں۔
’’ماعون‘‘ کی تفسیر میں علماء کے کئی قول ہیں۔ اس کی تفسیر بعض علماء سے زکوٰۃ نقل کی گئی ہے، لیکن اکثر علماء سے جو تفسیریں منقول ہیں ان کے موافق معمولی روز مرہ کے برتنے کی چیزیں ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ ہم حضورﷺ کے زمانہ میں ماعون کا مصداق یہ چیزیں قرار دیتے تھے: ڈول مانگا دے دینا، ہانڈی، کلہاڑی، ترازو اور اس قسم کی جو چیزیں ایک دوسرے کو مانگی دے دی جاتی ہیں کہ اپنا کام پورا کرکے و اپس کر دیں۔ حضرت ابوہریرہؓ حضورِ اقدسﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ ماعون سے مراد وہ چیزیں ہیں جن سے لوگ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کر دیتے ہیں، جیسا کہ کلہاڑی، دیگچی، ڈول وغیرہ۔ اور بھی متعدد روایات میں یہ مضمون کثرت سے ذکر کیاگیا۔ عکرمہ ؒ سے کسی نے ماعون کا مطلب پوچھا تو انہو ں نے فرمایا کہ اس کی جڑ تو زکوٰۃ ہے اور ادنیٰ درجہ چھلنی، ڈول، سوئی کا دینا ہے۔ (دُرِّمنثور)
اس سورتِ شریفہ میں کئی چیزوں پر تنبیہ کی گئی ہے۔ من جملہ ان کے یتیموں کے بارے میں خاص تنبیہ ہے کہ ہلاکت کے اَسباب میں سے یتیم کو دھکے دے کر نکال دینا بھی ہے۔ بہت سے لوگ یتیموں کے والی وارث بن کر ان کا مال اپنے تصرُّف میں لاتے ہیں اور جب وہ یا اس کی طرف سے کوئی مطالبہ کرے تو اس کو ڈانٹتے ہیں۔ ان پر ہلاکت اور عذابِ شدید میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ یہی نوع اس سورتِ شریفہ کا شانِ نزول بتایا جاتا ہے۔ قرآنِ پاک میں بہت کثرت سے یتیموں کے بارے میں تنبیہات اور آیات نازل ہوئی ہیں۔ چند آیات کی طرف اشارہ کرتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا کہ اللہ جَلَّ جَلاَلَہُ عَمَّ نَوَالُہ نے کس اہتمام سے اس پرتنبیہ بارہا فرمائی ہے:
۱۔ وَبِالْوَالِدَیْنِ اِحْسَانًا وَّذِی الْقُرْبٰٰی وَالْیَتٰمٰی وَالْمَسَاکِیْنِ (البقرۃ:ع۱۰)
۲۔ وَاٰتَی الْمَالَ عَلٰی حُبِّہٖ ذَوِی الْقُرْبٰی وَالیَتٰمٰی وَالْمَسَاکِیْنَ (البقرۃ:ع۲۲)
۳۔ قُلْ مَا اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَیْرٍ فَلِلْوَالِدَیْنِ وَلْاَقْرَبِیْنَ وَالْیَتٰمٰی (البقرۃ:ع۲۶)
۴۔ وَیَسْئَلُوْنَکَ عَنِ الْیَتٰمٰی قُلْ اِصْلاََحٌ لَّھُمْ خَیْرٌط (البقرۃ:ع ۲۷)
۵۔ وَاٰتُوْا الْیَتٰمٰی اَمْوَالَھُم (النساء: ع۱)
۶۔ وَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تُقْسِطُوْا فِی الْیَتٰمٰی (النساء : ع۱)
۷۔ وَابْتَلُوْا الْیَتٰمٰی (اِلیٰ قولہٖ) وَلَا تَاْکُلُوْھَا اِسْرًافًا وَّبِدَارً اَنْ یَّکْبَرُوْا ط (النساء:ع۱)
۸۔ وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَۃَ اُولُوا الْقُرْبٰی َوالْیَتٰمٰی الٓایۃ۔ (النساء:ع۱)
۹۔ اِنَّ الَّذِیْنَ یَاْکُلُوْنَ اَمْوَالَ الْیَتٰمٰی ظُلْمًا الآیۃ۔ (النساء:ع۱)
۱۰۔ وَبِالْوَالِدَیْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِی الْقُرْبٰی وَالْیَتٰمٰی الآیۃ۔ (النساء:ع۶)
۱۱۔ وَمَا یُتْلٰی عَلَیْکُمْ فِیْ الْکِتٰبِ فِیْ یَتٰمَی النِّسَائِ الآیۃ۔(النساء:ع۱۹)
۱۲۔ وَاَنْ تَقُوْمُوْا لِلْیَتٰمٰی بِالْقِسْطِ ط (النساء :ع ۱۹)
۱۳،۱۴۔ وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْیَتِیْمِ اِلاَّ بِالَّتِیْ ھِیَ اَحْسَنُ
(الأنعام :ع ۱۹، بني إسرائیل:ع۴)
۱۵۔ مَا اَفَآئَ اللّٰہُ عَلٰی رَسُوْلِہٖ الآیۃ۔ (الحشر :ع۱)
۱۶۔ وَیُطْمِعُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰی حُبِّہٖ مِسْکِیْنًا وَّیَتِیْمًا الآیۃ۔ (الدہر:ع۱)
۱۷۔ کَلاَّ بَلْ لَّا تُکْرِمُوْنَ الَیْتِیْمُ الآیۃ۔ (الفجر : ع۱)
۱۸۔ اَوْ اِطْعَامٌ فِیْ یَوْمٍ ذِی مَسْغَبَۃٍ یَّتِیْمًا ذَا مَقْرَبَۃٍ o (البلد:ع۱)
۱۹۔ اَلَمْ یَجِدْکَ یَتِیْمًا (الضحی)۲۰۔ فَاَمَّا اَلْیَتِیْمَ فَلاَ تَقْھَرْ (الضحی)
یہ بیس آیات نمونہ کے طور پر ذکر کی گئی ہیں اور آیات کی سورت اور رکوع بھی لکھ دیے ہیں۔ اگر کسی مترجَم قرآن شریف میں ان کو نکال کرترجمہ دیکھا جائے تومعلوم ہوگا کہ اللہ نے بار بار مختلف عنوانوں سے اس پر تنبیہ فرمائی ہے کہ یتیموں کے بارے میں ان کی اِصلاح، ان کی خیر خواہی، ان کے مال میں اِحتیاط، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ، ان کی اِصلاح اورفلاح کی کوشش، حتیٰ کہ اگر کسی یتیم لڑکی سے نکاح کرے تو اس کے مہر کو کم نہ کرنے پربھی تنبیہ کی گئی کہ کَس مپرسی کی وجہ سے اس کے مہر میں بھی کمی نہ کی جائے۔ حضورِ اقدسﷺ کا پاک ارشاد کئی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ میں اور وہ شخص جو کسی یتیم کی کفالت کرتا ہو جنت میںایسے قریب ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں۔ اس ارشاد پر حضورﷺ نے اپنی دو انگلیاں، شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی ملا کرا ن کی طرف اشارہ فرمایا کہ جیسے یہ دو قریب ہیں، ملی ہوئی ہیں، ایسے ہی میں اورو ہ شخص جنت میں قریب ہوں گے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ بیچ کی انگلی شہادت کی انگلی سے تھوڑی سی آگے نکلی ہوئی ہوتی ہے توا س صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ میرا درجہ نبوت کی وجہ سے تھوڑا ساآگے بڑھا ہوا ہوگا اور اس کے قریب ہی اس شخص کا درجہ ہوگا۔
ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص کسی یتیم کے سر پر (شفقت سے) ہاتھ پھیرے اور صرف اللہ کی رضاکے واسطے ایسا کرے تواس کا ہاتھ یتیم کے سر کے جتنے بالوں پر پھرے گا ہر بال کے بدلہ میں اس کو نیکیاں ملیںگی۔ اور جو شخص کسی یتیم لڑکے یا لڑکی پر احسان کرے تو میں اورو ہ شخص جنت میں اس طرح ہوںگے۔ وہی دو انگلیوں سے اشارہ فرمایا جیسا اوپر گزرا۔ اور بھی کئی حدیثوں میں مختلف عنوان سے یہی مضمون وارد ہواہے۔ (دُرِّمنثور)
ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ قبروں سے ایسے اٹھیں گے کہ ان کے منہ میں آگ بھڑک رہی ہوگی۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ! یہ کون لوگ ہوںگے؟ تو حضورﷺ نے آیاتِ گزشتہ میں سے نویں آیت تلاوت فرمائی { اِنَّ الَّذِیْنَ یَاکُلُوْنَ اَمْوَالَ الْیَتٰمٰی} جس کاترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ یتیموں کامال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ شبِ معراج میں حضورﷺ نے ایک قوم کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح سے بڑے بڑے ہیں، اور فرشتے ان پر مسلط ہیں کہ وہ ان کے ہونٹوں کو چیر کر ان میں آگ کے بڑے بڑے پتھر ٹھونس رہے ہیں کہ وہ آگ منہ سے داخل ہو کر پاخانہ کی جگہ سے نکلتی ہے اور وہ لوگ نہایت آہ و زاری سے چلا رہے ہیں۔ حضور ﷺ نے حضرت جبرئیل ؑ سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انھوں نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے تھے، ان کو آگ کھلائی جا رہی ہے۔
ایک حدیث میں ہے کہ چار قسم کے آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ نہ تو جنت میں داخل فرمائیں گے، نہ جنت کی نعمتیں ان کو چکھنا نصیب ہوں گی۔ ایک وہ شخص جو ہمیشہ شراب پیتا ہو، دوسرے سود خور، تیسرے وہ شخص جو ناحق یتیم کا مال کھائے، چوتھے وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرے۔ (دُرِّمنثور) حضرت اقدس شاہ عبدا لعزیز صاحب ؒ نے تفسیر میں تحریر فرمایا ہے کہ یتیموں پر احسان دو قسم کا ہے۔ ایک تو وہ ہے جو وارثوں پر واجب ہے، مثلاً: اس کے مال کی حفاظت کہ اس میں زراعت یاتجارت وغیرہ سے ترقی ہو تاکہ اس کا نفقہ اورضروریات پوری ہوسکیں، اور اس کی خوراک پوشاک وغیرہ کی خبر گیری، نیزاس کے لکھنے پڑھنے اور تعلیمِ آداب وغیرہ کی خبر گیری۔ دوسری قسم وہ ہے جو عام آدمیوں پر واجب ہے۔ اور وہ اس کی اِیذا کو ترک کرنا ہے، اور نرمی اورمہربانی سے اس سے پیش آنا ہے، محفلوں اور مجالس میں اپنے پاس بٹھانا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرنا، اپنی اولاد کی طرح اس کوگود میں لینا اور اس سے محبت ظاہر کرنا۔ اس لیے کہ جب وہ یتیم ہوگیا اس کاباپ نہ رہا تو حق تعالیٰ شا نہٗ نے سب بندوں کو حکم کیا کہ اس کے ساتھ باپ جیسا برتائو کریں اور اس کو اپنی اولاد کی طرح سمجھیں، تاکہ باپ کے مرنے کی وجہ سے جوعِجزِ حکمی اس کو لاحق ہوگیا اس قوتِ حقیقی کے ساتھ کہ ہزاروں آدمی اس کے باپ کی جگہ ہوجائیں، دور ہو جائے۔ پس یتیم بھی قرابتِ شرعی رکھتا ہے جیسا کہ دوسرے اَقارب قرابتِ عرفی رکھتے ہیں۔ (تفسیرِ عزیزی سورئہ بقرہ)
دوسرا مضمون جو آیتِ بالا میں خصوصی مذکور ہے وہ مسکین کے کھانے پر ترغیب نہ دینے پر تنبیہ ہے اور گویا بخل کے انتہائی درجہ کی طرف اشارہ ہے کہ خود تو وہ اپنا مال کیا خر چ کرتا وہ یہ بھی گوارہ نہیں کرتا کہ دوسرا بھی کوئی فقیروں پر خرچ کرے۔ قرآن پاک میں مسکینوں کے کھانا کھلانے پر بہت سی آیات میں ترغیب دی گئی جن میںسے بعض پہلے مذکور ہو چکی ہیں۔ سورئہ فجر میں ہے {کَلاَّ بَلْ لاَّ تُکْرِمُوْنَ الْیَتِیْمَ وَلَا تَحٰٓضُّوْنَ عَلٰی طَعَامِ الْمِسْکِیْنِo} اس میں اس پر بھی تنبیہ کی گئی کہ تم لوگ نہ تویتیموں کا اِکرام کرتے ہو نہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو۔
تیسری چیز جو آیتِ بالا میں ذکر کی گئی وہ ماعون کاروکنا ہے جس کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے۔ حضرتِ اقدس شاہ عبدالعزیز صاحب ؒ نے تحریر فرمایا کہ اس سورت کا نام ماعون اس وجہ سے ہے کہ یہ احسان کا ادنیٰ درجہ ہے۔ اور جب کہ احسان نہ کرنے کا ادنیٰ درجہ بھی موجبِ حجاب وعتاب ہے تو اعلیٰ درجہ یعنی حقوق اللہ اور حقوق الناس کے ضائع کرنے سے بطریقِ اولیٰ ڈرنا چاہیے۔
یہاں تک اس مضمون کے متعلق چند آیات ذکر کی گئی ہیں۔ آگے چند احادیث اس مضمون کے متعلق لکھی جاتی ہیں جن سے معلوم ہوگا کہ بخل اور مال کو جمع کرکے رکھنا کس قدر سخت چیز ہے۔
احادیث
۱۔ عَنْ أَبِيْ سَعِیْدٍ ؓقَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ ﷺ: خَصْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِيْ مُؤْمِنٍ، اَلْبُخْلُ وَسُوْئُ الْخُلْقِ۔
رواہ الترمذي، کذا في مشکاۃ المصابیح۔
حضورِ اقدسﷺ کا ارشاد ہے کہ دو خصلتیں ایسی ہیں کہ وہ مؤمن میں جمع نہیں ہوسکتیں۔ ایک تو بخل، دوسری بدخلقی۔
فائدہ: یعنی کوئی شخص مؤمن ہو کر بخیل بھی ہو اور بدخلق بھی یہ مؤمن کی شان ہرگز نہیں۔ ایسے شخص کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ خدانخواستہ ایسا نہ ہو کہ اسی سے ہاتھ دھو بیٹھیں کہ جیسا ہر خوبی دوسری خوبی کو کھینچتی ہے ایسے ہی ہر عیب دوسرے عیب کو کھینچتا ہے۔ دوسری حدیث میں اس سے بھی بڑھ کر حضورﷺ کاارشاد ہے کہ شُحّ (یعنی بخل کی اعلیٰ قسم) ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہوسکتی۔ (مشکاۃ المصابیح) کہ ان دونوں چیزوں کا اجتماع گویا ضدَّین کااجتماع ہے، جیسا کہ آگ اور پانی کا جمع ہونا کہ جونسی چیز غالب ہوگی وہ دوسرے کو فنا کردے گی۔
ایک حدیث میں آیا ہے کہ کوئی ولی ایسا نہیں ہوا جس میں اللہ نے دو عادتیں پیدا نہ کر دی ہوں۔ ایک سخاوت، دوسرے خوش خلقی۔ (کنز العمال) دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ کا کوئی ولی ایسا نہیں ہے جو سخاوت کا عادی نہ بنایا گیا ہو۔ (کنز العمال) اور بہت ظاہر بات ہے کہ اگر اللہ سے تعلق اور محبت ہے تو اس کی مخلوق پر خرچ کرنے کو بے اختیار دل چاہے گا کہ محبوب کے عزیز و اَقارب کی خاطر محبت کے لوازمات سے ہے۔ ا ور جب مخلوق اللہ کی عیال ہے تو ان پر خرچ کرنے کو ولی کا دل ضرور چاہے گا۔ اور اس کے عیال میں بھی جس کا تعلق اس کے ساتھ جتنا زیادہ قوی ہوگا اتنا ہی اس پر خرچ کرنے کو زیادہ چاہے گا۔ اور اگر نہ چاہے تو معلوم ہوا کہ مال کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کادعویٰ جھوٹ ہے۔
۲۔ عَنْ أَبِيْ بَکْرٍِ الصِّدِّیْقِ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ ﷺ: لَایَدْخُلُ الْجَنَّۃَ
حضرت ابو بکر صدیقؓ نے حضورِ اقدس ﷺ کا ارشاد نقل کیا کہ جنت میں نہ تو
خَبٌّ وَلَا بَخِیْلٌ وَلَا مَنَّانٌ۔
رواہ الترمذي، کذا في مشکاۃ المصابیح۔
چال باز (دھوکہ باز) داخل ہوگا، نہ بخیل، نہ صدقہ کرکے احسان رکھنے والا۔
فائدہ:
علماء نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان صفات کے ساتھ کوئی شخص بھی جنت میں داخل نہ ہوسکے گا۔ اگر کسی مؤمن میں یہ بری صفات خدانخواستہ پائی جاتی ہوں گی تو اوّل تو حق تعالیٰ شا نہٗ اس کو دنیا ہی میں ان سے توبہ کی توفیق عطا فرما ویں گے اور اگر یہ نہ ہوا تو اوّل جہنم میںداخل ہو کر ان صفات کا تنقیہ ہونے کے بعد جنت میں داخل ہوسکے گا، لیکن جہنم میںداخل ہونا چاہے تھوڑی ہی دیر کے لیے ہو، کیا کوئی معمولی اور آسان کام ہے؟ دنیاکی آگ میں تھوڑی دیر کے لیے ڈالاجانا کیا اثرات پیدا کرتا ہے؟ حالاںکہ یہ آگ جہنم کی آگ کے مقابلہ میں کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی۔
حضورِ اقدسﷺ کا ارشاد ہے کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا ستّرواں حصہ ہے۔ صحابہ? نے عرض کیا کہ حضور! یہ آگ کیا کچھ کم ہے؟ یہ تو خود ہی بہت کافی اذیت پہنچانے والی ہے۔ حضورﷺنے فرمایا کہ وہ اس سے انہتّردرجہ بڑھی ہوئی ہے۔ مشکاۃ المصابیح
ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جہنم میں سب سے کم عذاب والا شخص وہ ہوگا جس کو جہنم کی آگ کی صرف دو جوتیاں پہنائی جائیں گی اور ان کی وجہ سے اس کا دماغ ایسا جوش مارے گا جیساکہ ہنڈیا آگ پر جوش مارتی ہے۔ (مشکاۃ المصابیح) ایک حدیث میں آیا کہ اللہ نے جنتِ عدن کو اپنے دست ِمبارک سے بنایا۔ پھر اس کو آراستہ اور مزین کیا۔ پھر فرشتوں کو حکم فرمایا کہ اس میں نہریں جاری کریں اور پھل اس میں لٹکائیں۔ جب حق تعالیٰ شا نہٗ نے اس کی زیب وزینت کو ملاحظہ فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے عرش پر بلندی کی قسم! تجھ میں بخیل نہیں آسکتا۔ (کنز العمال)
۳۔ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّؓ قَالَ: انْتَھَیْتُ إِلَی النَّبِيِّ ﷺوَھُوَ جَالِسٌ فِی ظِلِّ الْکَعْبَۃِ، فَلَمَّا رَآنِيْ قَالَ: ھُمُ الأَخْسَرُوْنَ
حضرت ابوذرؓ فرماتے ہیں: میں ایک مرتبہ حضورﷺکی خدمت میں حاضر ہوا ۔ حضورﷺ کعبہ شریف کی دیوار کے سایہ
وَرَبِّ الْکَعْبَۃِ! فَقُلْتُ: فِدَاکَ أَبِيْ وَأُمِّيْ مَنْ ھُمْ؟ قَالَ: ھُمُ الأکْثَرُوْنَ مَالاً إِلاَّ مَنْ قَالَ ھٰکَذَا وَھٰکَذَا وَھٰکَذَا مِنْ بَیْنِ یَدَیْہِ وَمِنْ خَلْفِہٖ وَعَنْ یَمِیْنِہٖ وَعَنْ شِمَالِہٖ وَقَلِیْلٌ مَّا ھُمْ۔
متفق علیہ، کذا في مشکاۃ المصابیح۔
میں تشریف رکھتے تھے۔ مجھے دیکھ کر حضور ﷺ نے فرمایا کہ کعبہ کے رب کی قسم! وہ لوگ بڑے خسارہ میں ہیں۔ میں نے عرض کیا: میرے ماں باپ آپ پر قربان، کون لوگ؟ حضور ﷺ نے فرمایا کہ جن کے پاس مال زیادہ ہو، مگر وہ لوگ جو اس طرح،
اس طرح، اس طرح (خرچ) کریں، اپنے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے، لیکن ایسے آدمی بہت کم ہیں۔
فائدہ: حضرت ابوذرؓ زاہدین صحابہ میں ہیں جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا۔ ان کو دیکھ کر یہ ارشاد حقیقتاً ان کی تسلی تھی کہ اپنے فقر و زہد پر کسی وقت بھی خیال نہ کریں۔ یہ مال ومتاع کی کثرت فی ذاتہٖ کوئی محبوب چیز نہیں، بلکہ بڑے خسارے اور نقصان کی چیز ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ اللہ سے غفلت کا سبب بنتی ہے۔ روز مرّہ کا مشاہدہ ہے کہ بغیر تنگدستی کے اللہ کی طرف رجوع بہت ہی کم ہوتا ہے۔ البتہ جن لوگوں کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے، اور وہ ضرورت کے مواقع میں جہاں اور جس طرف ضرورت ہو چاروں طرف بخشش کا ہاتھ پھیلاتے ہوں، ان کے لیے مال مضر نہیں ہے۔
لیکن حضورﷺ نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ ایسے آدمی کم ہیں۔ عام طور سے یہی ہوتاہے کہ مال کی کثرت ہوتی ہے، فسق وفجور، آوارگی، عیاشی اپنے ساتھ لاتی ہے۔ اور بے محل خرچ کرنا ، نام و نمود پر صَرف کرنا تو دولت کے ادنیٰ کرشموں میں سے ہے۔ بیاہ شادیوں اور دوسری تقریبات پر بے جا اور بے محل ہزاروں روپیہ خرچ کر دیا جائے گا، لیکن اللہ کے نام پرضرورت مندوں اور بھوکوں پرخرچ کرنے کی گنجایش ہی نہ نکلے گی۔
ایک حدیث میں ہے کہ جو لوگ دنیا میں مال دار زیادہ ہیں وہی لوگ آخرت میں کم سرمایہ والے ہیں، مگر وہ شخص جو حلال ذریعہ سے کمائے اور یوں یوں خرچ کر دے۔ (کنزالعمال) پہلی حدیث کی طرح یوں یوں کا اشارہ ادھر ادھر خرچ کرنے کی طرف ہے۔ حقیقت میں مال اُس کے لیے زینت اور عزت ہے جو اِس کو ادھر ادھر خرچ کردے۔ اور جوگن گن کر باندھ باندھ کررکھے، اس کے لیے یہ ہر قسم کی آفات کاپیش خیمہ ہے۔ اس کو بھی ہلاک کرتا ہے اور خود بھی اس کے پاس سے ضائع ہوتا ہے۔ یہ بے مروّت کسی شخص کو دین یا دنیا کا فائدہ اس وقت تک نہیں پہنچاتا جب تک اس کے پاس سے جدا نہ ہو۔
۴۔ عَنْ أَبِيْ ھُرَیْرَۃؓ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ ﷺ اَلسَّخِيُّ قَرِیْبٌ مِّنَ اللّٰہِ، قَرِیْبٌ مِّنَ الْجَنَّۃِ، قَرِیْبٌ مِّنَ النَّاسِ، بَعِیْدٌ مِنَ النَّارِ۔ وَالْبَخِیْلُ بَعِیْدٌ مِّنَ اللّٰہِ، بَعِیْدٌ مِّنَ الْجَنَّۃِ، بَعِیْدٌ مِّنَ النَّاسِ، قَرِیْبٌ مِنَ النَّارِ، وَلَجَاھِلٌ سَخِيٌّ أَحَبُّ إِلَی اللّٰہِ مِنْ عَابِدٍ بَخِیْلٍ۔
رواہ الترمذي، کذا في مشکاۃ المصابیح۔
حضورِاقدسﷺکا ارشاد ہے کہ سخی آدمی اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے، جہنم سے دور ہے۔ اور بخیل آدمی اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، آدمیوں سے دور ہے اور جہنم سے قریب ہے۔ بے شک جاہل سخی اللہ کے نزدیک عابد بخیل سے زیادہ محبوب ہے۔
فائدہ: یعنی جو شخص عبادت بہت کثرت سے کرتا ہو، نوافل بہت لمبی لمبی پڑھتا ہو، اس سے وہ شخص اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے جو نوافل بہت کم پڑھتا ہو لیکن سخی ہو۔ عابد سے مراد نوافل کثرت سے پڑھنے والا ہے۔ فرائض کا پڑھنا تو ہر شخص کے لیے ضروری ہے چاہے سخی ہو یا نہ ہو۔
امام غزالی ؒ نے نقل کیا ہے کہ حضرت یحییٰ بن زکریاعلی نبینا و علیہما الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ شیطان سے دریافت فرمایا کہ تجھے سب سے زیادہ کو ن شخص محبوب ہے اور سب سے زیادہ نفرت کس سے ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ محبت مؤمن بخیل سے ہے اور سب سے زیادہ نفرت فاسق سخی سے ہے۔ انھوں نے فرمایا: یہ کیا بات ہے؟ اس نے عرض کیا کہ بخیل اپنے بخل کی وجہ سے مجھے بے فکر رکھتا ہے۔ یعنی اس کا بخل ہی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، لیکن فاسق سخی پرمجھے ہر وقت فکرسوار رہتا ہے کہ کہیں حق تعالیٰ شا نہٗ اس کی سخاوت کی وجہ سے اس سے درگزر نہ فرما ویں۔ (اِحیاء العلوم)
یعنی حق تعالیٰ شا نہٗ اس کی سخاوت کی وجہ سے کسی وقت اس سے راضی ہوگئے تو اس کے دریائے مغفرت و رحمت میں عمر بھر کے فسق و فجور کی کیا حقیقت ہے۔ وہ سب کچھ معاف فرما سکتا ہے۔ ایسی صورت میں میری عمر بھر کی محنت جو اس سے گناہ صادر کرانے میں کی تھی، ساری ضائع ہوگئی۔
ایک حدیث میںہے کہ جو شخص سخاوت کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ حسنِ ظن کی وجہ سے کرتا ہے۔ اور جو بخل کرتا ہے وہ حق تعالیٰ شا نہٗ کے ساتھ بدظنی سے کرتا ہے۔ (کنزالعمال) حسنِ ظن کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس مالک نے یہ عطا فرمایا وہ پھر بھی عطا فرماسکتا ہے، اور ایسے شخص کے اللہ سے قریب ہونے میں کیا تردد ہے؟ اور بدظنی کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ختم ہوگئے تو پھر کہاں سے آئیں گے۔ ایسے شخص کا اللہ سے دور ہونا ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خزانہ کو بھی محدود سمجھتا ہے۔ حالاںکہ آمدنی کے اسباب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور ان اسباب سے پیداوار کا ہونا اسی کے قبضۂ قدرت میں ہے ۔ وہ نہ چاہے تو دکان دار ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھا رہے۔ کاشت کار بوئے اور پیداوار نہ ہو۔ اور جب کہ یہ سب اسی کی عطا کی وجہ سے ہے پھر اس کا کیا مطلب کہ ’’پھر کہاں سے آئے گا؟‘‘ مگر ہم لوگ زبان سے اس کا اِقرار کرنے کے بعد دل سے یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ شا نہٗ ہی کی عطا ہے، ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں۔ اور صحابہ کرام دل سے یہ سمجھتے تھے کہ یہ سب اسی کی عطاء ہے، جس نے آج دیا وہ کل بھی دے گا۔ اس لیے ان کو سب کچھ خرچ کر دینے میں ذرا بھی تامُّل نہ ہوتا تھا۔
۵۔ عَنْ أَبِيْ ھُرَیْرَۃَ ؓقَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ ﷺ: السَّخَآئُ شَجَرَۃٌ فِيْ الْجَنَّۃِ، فَمَنْ کَانَ سَخِیًّا اَخَذَ بِغُصْنٍ مِنْھَا، فَلَمْ یَتْرُکْہُ الْغُصْنُ حَتّی یُدْخِلَہُ الْجَنَّۃَ۔ وَالشُّحُّ شَجَرَۃٌ فِيْ النَّارِ فَمَنْ
حضورِ اقدسﷺ کا ارشاد ہے کہ سخاوت جنت میں ایک درخت ہے۔ پس جو شخص سخی ہوگا وہ اس کی ایک ٹہنی پکڑلے گا جس کے ذریعہ سے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور بخل جہنم کاایک درخت ہے۔ جو شخص
کَانَ شَحِیْحًا أَخَذَ بِغُصْنٍ مِنْھَا، فَلَمْ یَتْرُکْہُ الْغُصْنُ حَتَّی یُدْخِلَہُ النَّارَ۔
رواہ البیھقي في شعب الإیمان، کذا في مشکاۃ المصابیح۔
شحیح (بخیل) ہوگا وہ اس کی ایک ٹہنی پکڑلے گا، یہاںتک کہ وہ ٹہنی اس کو جہنم میں داخل کرکے رہے گی۔
فائدہ: شُحّ بخل کا اعلیٰ درجہ ہے جیسا کہ پہلی فصل کی آیات میں نمبر (۲۸) پرگزر چکا ہے۔ مطلب ظاہر ہے کہ جب بخل جہنم کا درخت ہے تواس کی ٹہنی پکڑ کر جو شخص چڑھے گا وہ جہنم ہی میں پہنچے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام سخا ہے، سخاوت اسی سے پیدا ہوئی ہے۔ اور جہنم میںایک درخت ہے جس کا نام شُحّ ہے، شُحّ اسی سے پیدا ہوا ہے۔ جنت میںشحیح داخل نہ ہوگا۔ (کنز العمال) یہ پہلے متعدد مرتبہ معلوم ہوچکا کہ شُحّ بخل کا اعلیٰ درجہ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ سخاوت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کی ٹہنیاں دنیا میں جھک رہی ہیں۔ جو شخص اس کی کسی ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے وہ ٹہنی اس کو جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ اور بخل جہنم کے درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کی ٹہنیاں دنیا میں جھک رہی ہیں۔ جو شخص اس کی کسی ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے وہ ٹہنی اس کو جہنم تک پہنچا دیتی ہے۔ (کنز العمال) یہ ظاہر چیز ہے کہ جو سڑک اسٹیشن پر جاتی ہے جب آدمی اس سڑک پر چلتا رہے گا تولا محالہ کسی وقت اسٹیشن پر پہنچے گا۔ اسی طرح سے یہ ٹہنیاں جن درختوں کی ہیں جب ان کو کوئی پکڑ کر چڑھے گا تو جہاں وہ درخت کھڑا ہے وہاں پہنچ کر رہے گا۔
۶۔ عَنْ أَبِيْ ھُرَیْرَۃَؓ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ ﷺ: شَرُّ مَا فِيْ الرَّجُلِ شُحٌّ ھَالِعٌ وَجُبْنٌ خَالِعٌ۔
رواہ أبو داود وکذا في مشکاۃ المصابیح۔
حضورِ اقدسﷺ کا ارشاد ہے کہ بدترین عادتیں جو آدمی میں ہوں (دو ہیں)۔ ایک وہ بخل ہے جو بے صبر کر دینے والا ہو، دوسرے وہ نامردی اور خوف جو جان نکال دینے والا ہو۔
فائدہ: ان دو عیبوں کی طرف اللہ نے اپنے کلام میں بھی تنبیہ فرمائی ہے۔ چناںچہ ارشاد ہے:
اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ ھَلُوْعًا o اِذَا مَسَّہُ الشَّرُّ جَزُوْعًا o وَّاِذَا مَسَّہُ الْخَیْرُ مَنُوْعًا o اِلاَّ الْمُصَلِّیْنَ o الَّذِیْنَ ھُمْ عَلٰی صَلاََتِھِمْ دَائِمُوْنَ o وَالَّذِیْنَ فِیْ اَمْوَالِھِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ o لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ o وَالَّذِیْنَ یُصَدِّقُوْنَ بِیَوْمِ الدِّیْنَ o وَالَّذِیْنَ ھُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّھِمْ مُّشْفِقُوْنَ o اِنَّ عَذَابَ رَبِّھِمْ غَیْرُ مَاْمُوْنٍ o وَالَّذِیْنَ ھُمْ لِفُرُوْجِھِمْ حٰفِظُوْنَ o اِلاَّ عَلٰی اَزْوَاجِھِمْ اَوْ مَا مَلَکْتْ اَیْمَانُھُمْ فَاِنَّھُمْ غَیْرُ مَلُوْمِیْنَ o فَمَنِ ابْتَغٰی وَرَآئَ ذٰلِکَ فَاُوْلٰٓئِکَ ھُمُ الْعٰدُوْنَ o وَالَّذِیْنَ ھُمْ لِاَمٰنٰتِھِمْ وَعَھْدِھِمْ رَاعُوْنَ o وَالَّذِیْنَ ھُمْ بِشَھٰدٰتِھِمْ قَآئِمُوْنَ o وَالَّذِیْنَ ھُمْ عَلٰی صَلٰوتِھِمْ یُحَافِظُوْنَ o اُولٰئِکَ فِیْ جَنّٰتٍ مُّکْرَمُوْنَ o (المعارج : ع۱)
’’بے شک انسان کم ہمت (تھوڑے اورکچے دل کا) پیدا ہوا ہے۔ جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے توجزع فزع کرنے لگتا ہے۔ اور جب اس کو خیر (مال) پہنچتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ مگر وہ نمازی جو اپنی نماز پر پابندی کرنے والے ہیں۔ اورجن کے مالوں میں سوال کرنے والوںکے لیے اور سوال نہ کرنے والوںکے لیے مقررہ حق ہے۔ اور وہ لوگ جو قیامت کے دن کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں۔ بے شک ان کے ربّ کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں۔ (یقینًا اس سے ہر شخص کو ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے) اور وہ لوگ جواپنی شرم گاہوں کو (حرام جگہ سے) محفوظ رکھتے ہیں۔ لیکن اپنی بیبیوں اور باندیوں سے (حفاظت کی ضرورت نہیں) کیوں کہ ان پر ان میں کوئی الزام نہیں۔(یعنی ان لوگوں پر بیویوں اور باندیوں سے صحبت کرنے میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے) ہاں جو لوگ ان کے علاوہ (اور جگہ شہوت پوری کرنے) کے طلب گارہوں وہ حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اپنے (سپرد کی ہوئی) امانتوں اور اپنے عہد (قول و قرار)کا خیال رکھنے والے ہیں۔ اور اپنی گواہیوں کو ٹھیک ٹھیک ادا کرتے ہوں۔ اور جو اپنی فرض نماز کی پابندی کرنے والے ہوں۔ یہی لوگ ہیں جو جنتوں میں عزت سے داخل ہوںگے ۔
فقط یہ ان آیات کا ترجمہ ہے اور اس قسم کا پورا مضمون اس کے قریب قریب دوسری جگہ سورئہ مؤمنون کے شروع میں بھی گزر چکا ہے۔
حضرت عمران بن حصینؓفرماتے ہیں کہ حضورِ اقدسﷺ نے میرے عمامہ کا سِرا پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ عمران! حق تعالیٰ شا نہٗ کو خرچ کرنا بہت پسند ہے اور روک کررکھنا ناپسند ہے۔ تُو خرچ کیا کر اور لوگوں کو کھلایا کر۔ کسی کو مضرت نہ پہنچا کہ تجھ پر تیری طلب میں مضرت ہونے لگے گی۔ غور سے سن! حق تعالیٰ شا نہٗ شبہات کے وقت تیز نظر کو پسند کرتے ہیں۔ (یعنی جس نظر میں جائز ناجائز کا شبہ ہو اس میں باریک نظر سے کام لیناچاہیے، ویسے ہی سرسری طور پر جو چاہے کرگزرنا نہ ہو) اور شہوتوں کے وقت کامل عقل کو پسند کرتے ہیں (کہ شہوت کے غلبہ میں عقل نہ کھو دے)۔ اور سخاوت کو پسند کرتے ہیں چاہے چندکھجوریں ہی خرچ کرے۔ (یعنی اپنی حیثیت کے موافق زیادہ نہ ہوسکے تو کم میں شرم نہ کرے، جو ہوسکے خرچ کرتا رہے) اوربہادری کو پسند کرتے ہیں چاہے سانپ اور بچھو ہی کے قتل میںکیوں نہ ہو۔ (کنز العمال) لہٰذا ذرا سی خوف کی چیز سے ڈرجانا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اگر دل میں خوف پیدا بھی ہو تو اس کا اظہار نہ کرنا چاہیے، بلکہ قوت کے ساتھ اس کو دفع کر نا چاہیے۔ حضورِ اقدسﷺ سے جو دعائیں امت کی تعلیم کے لیے منقول ہیں ان میں نامردی سے پناہ مانگنا بھی نقل کیا گیا ہے اور متعدد دعائوں میں اس سے پناہ مانگنا نقل کیا گیا۔ (بخاری)
۷۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ?قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰہِ ﷺ: لَیْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِيْ یَشْبَعُ وَجَارُہٗ جَائِعٌ إِلَی جَنْبِہٖ۔
حضورﷺ کا پاک ارشاد ہے کہ وہ شخص مؤمن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھانا کھالے اور پاس ہی اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔
رواہ البیھقي في الشعب، کذا في مشکاۃ المصابیح۔
فائدہ: یقینا جس شخص کے پاس اتناہے کہ وہ پیٹ بھر کر کھا سکتا ہے اور پاس ہی بھوکا پڑوسی ہے، تواس کے لیے ہرگز ہرگز زیبا نہیں کہ خود پیٹ بھر کر کھائے اور وہ غریب بھوک میں تلملاتا رہے۔ ضروری ہے کہ اپنے پیٹ کو کچھ کم پہنچائے اور پڑوسی کی بھی مدد کرے۔ ایک حدیث میں ہے: حضورﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا جو خود پیٹ بھرکر رات گزارے اور اس کو یہ بات معلوم ہے کہ اس کا پڑوسی اس کے برابر میں بھوکا ہے۔ (الترغیب والترہیب) ایک اور حدیث میں حضورﷺ کا ارشاد ہے کہ قیامت میں کتنے آدمی ایسے ہوںگے جو اپنے پڑوسی کا دامن پکڑے اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے: یااللہ! اس سے پوچھیں کہ اس نے اپنا دروازہ بند کرلیا تھا اور مجھے اپنی ضرورت سے زائد جو چیز ہوتی تھی وہ بھی نہ دیتا تھا۔ (الترغیب والترہیب) ایک اور حدیث میں حضورﷺ کا ارشاد وارد ہوا ہے: لوگو! صدقہ کرو، میں قیامت کے دن اس کی گواہی دوں گا۔ شاید تم میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے پاس رات کو سیر ہونے کے بعد بچ رہے اور اس کا چچا زاد بھائی بھوک کی حالت میں رات گزارے۔ تم میں شاید کچھ ایسے بھی لوگ ہوںگے جو خود تو اپنے مال کو بڑھاتے رہیں اور ان کامسکین پڑوسی کچھ نہ کما سکے۔ (کنز العمال)
ایک اور حدیث میں حضورﷺ کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ آدمی کے بخل کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ یوں کہے کہ میںا پنا حق پورا کاپورا لوں گا، اس میں سے ذرا سا بھی نہیں چھوڑوں گا۔ (کنز العمال) یعنی تقسیم وغیرہ میں رشتہ داروں سے ہو یا پڑوسیوں سے اپنا پورا حق وصول کرنے کی فکر میں لگا رہے، ذرا ذرا سی چیز پر کُنج و کائو کرے، یہ بھی بخل کی علامت ہے۔ اگر تھوڑا بہت دوسرے کے پاس چلاہی جائے گا تو اس میں کیا مرجائے گا۔
۸۔ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِيْ ھُرَیْرَۃَ ? قَالَا: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِﷺ: عُذِّبَتْ امْرَأَ ۃٌ فِيْ ھِرَّۃٍ أَمْسَکَتْھَا حَتَّی مَاتَتْ مِنَ الْجُوْعِ فَلَمْ تَکُنْ تُطْعِمُھَا وَلاَ تُرْسِلُھَا فَتَاکُلَ مِنْ خُشَاشِ الأَرْضِ۔
متفق علیہ، کذا في مشکاۃ المصابیح۔
حضرت ابنِ عمر اور حضرت ابوہریرہ ? دونوں نے حضورﷺ کایہ ارشاد نقل کیا کہ ایک عورت کو اس پر عذاب کیاگیا کہ اس نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا جو بھوک کی وجہ سے مر گئی۔ نہ تو اس نے اس کو کھانے کو دیا، نہ ا س کو چھوڑا کہ وہ زمین کے جانوروں (چوہے وغیرہ) سے اپنا پیٹ بھرلیتی۔
فائدہ: جو لوگ جانورںکو پالتے ہیں ان کی ذمہ داری بہت سخت ہے کہ وہ بے زبان جانور اپنی ضروریات کو ظاہر بھی نہیں کرسکتے، ایسی حالت میں ان کے کھانے پینے کی خبر گیری بہت اہم اور ضروری ہے۔ اس میں بخل سے کام لینا اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کرنے کے لیے تیار کرناہے۔ بہت سے آدمی جانوروں کے پالنے کا تو بڑا شوق رکھتے ہیں، لیکن ان کے گھاس دانہ پر خرچ کرتے ہوئے جان نکلتی ہے۔ حضورِ اقدسﷺ سے مختلف احادیث میں مختلف عنوانات سے یہ مضمون نقل کیاگیا کہ ان جانورں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو۔
ایک مرتبہ حضورِ اقدسﷺ تشریف لے جا رہے تھے راستہ میں ایک اونٹ نظرِاقدس سے گزرا جس کا پیٹ کمر سے لگ رہا تھا (بھوک کی وجہ سے یا دُبلے پن کی وجہ سے)۔ حضورﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہا کرو، ان کی اچھی حالت میں ان پر سوار ہوا کرو اور اچھی حالت میں ان کو کھایا کرو۔
حضورﷺکی عادتِ شریفہ یہ تھی کہ استنجے کے لیے جنگل میں تشریف لے جایا کرتے۔ کسی باغ میں یا کسی ٹیلہ وغیرہ کی آڑ میں ضرورت سے فراغت حاصل کرتے۔ ایک مرتبہ اس ضرورت سے ایک باغ میں تشریف لے گئے تو وہاں ایک اونٹ تھا، جو حضورﷺکو دیکھ کر بِڑانے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوگئے (ایک معرو ف چیز ہے کہ ہر مصیبت زدہ کا کسی غم خوار کو دیکھ کر دل بھر آیاکرتا ہے)۔ حضورﷺ اس کے پاس تشریف لے گئے، اس کے کانوں کی جڑ پر شفقت کا ہاتھ پھیرا جس سے وہ چپکا ہوا۔ حضورﷺ نے فرمایا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک انصاری تشریف لائے اور عرض کیا کہ میرا ہے۔ حضورﷺ نے فرمایا: تم اس اللہ سے جس نے تمہیں اس کا مالک بنایا، ڈرتے نہیں ہو؟ اونٹ تمہاری شکایت کرتا ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور کام زیادہ لیتے ہو۔ ایک اور حدیث میںہے کہ ایک مرتبہ حضورﷺ نے ایک گدھے کو دیکھا کہ اس کے منہ پر داغ دیاگیا۔ حضورﷺنے فرمایا کہ تم کو اب تک یہ معلوم نہیں کہ میں نے اس شخص پر لعنت کی ہے جو جانور کے منہ کو داغ دے یا منہ پر مارے۔
’’ابوداود شریف‘‘ میں یہ روایات ذکر کی گئیں۔ ان کے علاوہ اور بھی مختلف روایات میں اس پر تنبیہ کی گئی ہے کہ جانوروں کی خبر گیری میں کوتاہی نہ کی جائے۔ اور جب جانوروں کا یہ حال ہے اور ان کے بارے میں یہ تنبیہات ہیں تو آدمی جو اشرف المخلوقات ہے،اس کا حال اَظہر ہے اور زیادہ اہم ہے۔ حضورﷺ کا ارشاد ہے کہ آدمی کے گناہ کے لیے یہ کافی ہے کہ جس کی روزی اپنے ذمہ ہے اس کو ضائع کرے۔ اس کے لیے اگر کسی جانور کو اپنی کسی ضرورت سے روک رکھا ہے تواس کے کھانے میں کنجوسی کرنااور یہ سمجھنا کہ کون جانے کس کو خبر ہوگی، اپنے اوپر سخت ظلم ہے۔ جاننے والا سب کچھ جانتا ہے اور لکھنے والے ہر چیز کی رپورٹ لکھتے ہیں، چاہے کتنی ہی مخفی کی جائے۔ اور یہ آفت بخل سے آتی ہے کہ جانوروں کو اپنی ضرورت سے، سواری کی ہو یا کھیتی کی، دُودھ کی ہو یا کوئی اور کام لینے کی ہو پالتے ہیں، لیکن کنجوسی سے ان پر پیسہ خرچ کرتے ہوئے دَم نکلتا ہے۔
۹۔ عَنْ أَنَسٍؓ عَنِ النَّبِيّ ﷺ قَالَ: یُجَاؤُ بِابْنِ آدَمَ یَوْمَ الْقِیَامَۃِ کَأنَّہٗ بَذْجٌ، فَیُوْقَفُ بَیْنَ یَدَيِ اللّٰہِ فَیَقُوْلُ لَہُ: أَعْطَیْتُکَ وَخَوَّلْتُکَ وَأَنْعَمْتُ عَلَیْکَ فَمَا صَنَعْتَ؟ فَیَقَُوْلُ: یَا رَبِّ! جَمَعْتُہُ وَ ثَمَّرْتُہُ وَتَرَکْتُہُ أَکْثَرَ مَاکَانَ، فَأَرْجِعْنِيْ آتِکَ بِہٖ کُلِّہٖ۔ فَیَقُوْلُ: أَرِنِيْ مَا قَدَّمْتَ؟ فَیَقُوْلُ: رَبِّ! جَمَعْتُہُ وََثَمَّرْتُہُ وَ تَرَکْتُہُ أَکْثَرَ مَا کَانَ، فَأَرْجِعْنِيْ آتِکَ بِہٖ کُلِّہٖ۔ فَاِذَا عَبْدٌ لَّمْ یُقَدِّمْ خَیْرًا، فَیُمْضَی بِہٖ إِلَی النَّارِ۔
رواہ الترمذي وضعفہ، کذا في مشکاۃ المصابیح۔
حضورِ اقدسﷺ کاارشاد نقل کیاگیا کہ قیامت کے دن آدمی ایسا (ذلیل وضعیف) لایا جائے گا جیسا کہ بھیڑ کا بچہ ہوتا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ ارشاد ہوگا کہ میں نے تجھے مال عطا کیا، حشم و خدم دیے، تجھ پر نعمتیں برسائیں، تو نے ان سب انعامات میں کیا کارگزاری کی؟ وہ عرض کرے گا کہ میں نے خوب مال جمع کیا، اس کو (اپنی کوشش سے) بہت بڑھایا، اور جتنا شروع میں میرے پاس تھا اس سے خدمت میں حاضر کر دوں۔ ارشاد ہوگا: مجھے تُو وہ بتا جو تُو نے زندگی میں (ذخیرہ کے طور پر آخرت کے لیے) آگے بھیجا ہو۔
وہ پھر اپنا پہلا کلام دہرائے گا کہ میرے پروردگار! میں نے اس کو خوب جمع کیا اور خوب بڑھایا اور جتنا شروع میں تھا اس سے بہت زیادہ کرکے چھوڑ آیا۔ آپ مجھے دنیا میں واپس کر دیں میں وہ سب لے کر حاضر ہوں (یعنی خوب صدقہ کروں تاکہ وہ سب یہاںمیرے پاس آجائے)۔ چوںکہ اس کے پاس کوئی ذخیرہ ایسا نہ نکلے گا جو اس نے اپنے لیے آگے بھیج دیا ہو، اس لیے اس کو جہنم میں پھینک دیاجائے گا۔
فائدہ: ہم لوگ تجارت میں، زراعت میں اور دوسرے ذرائع سے روپیہ کمانے میں جتنی محنت اور درد سری کرکے جمع کرتے ہیں، وہ سب اسی لیے ہوتا ہے کہ کچھ ذخیرہ اپنے پاس موجود رہے جو ضرورت کے وقت کام آئے، نہ معلوم کس وقت کیا ضرورت پیش آجائے، لیکن جو اصل ضرورت کا وقت ہے، اور اس کا پیش آنا بھی ضروری اور اس میں اپنی سخت اِحتیاج بھی ضروری ہے،اور یہ بھی یقینی کہ اس وقت صرف وہی کام آئے گا جو اپنی زندگی میں خدائی بنک میں جمع کر دیا گیاہو کہ وہ تو جمع شدہ ذخیرہ بھی پوراکا پورا ملے گا اور اس میں اللہ کی طرف سے اضافہ بھی ہوتا رہے گا، لیکن اس کی طرف بہت ہی کم اِلتفات کرتے ہیں۔ حالاںکہ دنیا کی یہ زندگی چاہے کتنی ہی زیادہ ہو جائے، بہرحال ایک دن ختم ہوجانے والی ہے اورآخرت کی زندگی کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی میںاگر اپنے پاس سرمایہ نہ رہے تو اس وقت محنت اور مزدوری بھی کی جاسکتی ہے،بھیک مانگ کر بھی زندگی کے دن پورے کیے جاسکتے ہیں، لیکن آخرت کی زندگی میں کوئی صورت کمائی کی نہیں ہے، وہاں صرف وہی کام آئے گا جو ذخیرہ کے طور پر آگے بھیج دیا گیا۔
ایک اور حدیث میں حضورﷺکا ارشاد وارد ہے کہ میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اس کی دونوںجانب تین سطریں سونے کے پانی سے لکھی ہوئی دیکھیں۔ پہلی سطر میں لَا إِلٰـہَ إِلاَّ اللّٰہُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہِلکھا تھا، دوسری سطر میں مَا قَدَّمْنَا وَجَدْنَا، وَمَا أَکَلْنَا رَبِحْنَا، وَمَاخَلَّفْنَا خَسِرْنَا لکھا تھا (جو ہم نے آگے بھیج دیا وہ پالیا اور جو دنیامیں کھایا وہ نفع میں رہا اورجو کچھ چھوڑآئے وہ نقصان میں رہا) اور تیسری سطر میں لکھاتھا أُمَّۃٌ مُذْنِبَۃٌ وَرَبٌّ غَفُوْرٌ۔ (امت گناہ گار اور ربّ بخشنے والا ہے) (برکاتِ ذکر)
پہلی فصل کی آیات میں نمبر (۲) پر گزر چکا ہے کہ اس دن نہ تجارت ہے، نہ دوستی، نہ سفارش۔ اسی فصل میں نمبر (۳ ) پر اللہ کاارشاد گزرا ہے کہ ہر شخص یہ دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو فرشتے تویہ پوچھتے ہیں کہ کیا ذخیرہ اپنے حساب میں جمع کرایا؟ کیا چیز کل کے لیے بھیجی؟ اور آدمی یہ پوچھتے ہیں: کیامال چھوڑا؟ (مشکاۃ المصابیح)
ایک اور حدیث میں ہے کہ حضورﷺ نے دریافت فرمایا کہ تم میں کون شخص ایسا ہے جس کو اپنے وارث کا مال اپنے سے زیادہ محبوب ہو؟ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کو ا پنا مال اپنے وارث سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ حضورﷺنے فرمایا: آدمی کا اپنا مال وہ ہے جو اس نے آگے بھیج دیا۔ اور جو چھوڑ گیا وہ اس کا مال نہیں اس کے وارث کا مال ہے۔ (مشکاۃ المصابیح عن البخاري)
ایک اور حدیث میں حضورﷺکا ارشاد وارد ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ میرا مال، میرا مال۔ اس کے مال میں سے اس کے لیے صرف تین چیزیں ہیں: ۱۔ جو کھا کر ختم کر دیا ۲۔ یا پہن کر پرانا کردیا ۳۔ یا اللہ کے یہاں اپنے حساب میں جمع کرا دیا۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اس کامال نہیں ہے، لوگوں کے لیے چھوڑ جائے گا۔ (مشکاۃ المصابیح)
اور بڑالطف یہ ہے کہ آدمی اکثر ایسے لوگوں کے لیے جمع کرتا ہے، محنت اٹھاتا ہے، مصیبت جھیلتا ہے، تنگی برداشت کرتا ہے، جن کو وہ اپنی خواہش سے ایک پیسہ دینے کا روادار نہیں ہے، لیکن جمع کرکے چھوڑ جاتا ہے اور مقدرات اُنہی کو سارے کا وارث بنا دیتے ہیں جن کوو ہ ذرا سا بھی دینا نہ چاہتا تھا۔ اَرطاۃ بن سہیۃ ؒ کا جب انتقال ہونے لگا تو انھوں نے چندشعر پڑھے جن کاترجمہ یہ ہے کہ
آدمی کہتا ہے کہ میں نے بہت مال جمع کیا، لیکن اکثر کمانے والا دوسروں کے یعنی وارثوں کے لیے جمع کرتا ہے۔ وہ خود تو اپنی زندگی میں اپنا بھی حساب لیتا رہتا ہے کہ کتنا کہاں خرچ ہوا،کتنا کہاں ہوا؟ لیکن بعد میں ایسے لوگوں کی لوٹ کے لیے چھوڑا جاتا ہے جن سے حساب بھی نہیں لے سکتا کہ سارا کہاں اڑا دیا؟ پس اپنی زندگی میں کھالے اورکھلا دے، اور بخیل وارث سے چھین لے۔ آدمی خود تو مرنے کے بعد نامراد رہتا ہے (کوئی اس کو اس مال میں یاد نہیں رکھتا) دوسرے لوگ اس کو کھاتے اڑاتے ہیں۔ آدمی خود اس مال سے محروم ہو جاتا ہے اور دوسرے لوگ اس سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں۔ (اِتحاف)
ایک حدیث میں یہ قصہ جو اوپر کی حدیث میں ذکر کیا گیا دوسرے عنوان سے وارد ہوا ہے کہ حضورﷺ نے ایک مرتبہ صحابہ? سے دریافت فرمایا: تم میں کوئی ایسا ہے جس کو اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبوب ہو؟ صحابہ نے عر ض کیا: یارسول اللہ! ہم میںہر شخص ایسا ہی ہے جس کو اپنا مال زیادہ محبوب ہے۔ حضورﷺ نے فرمایا: سوچ کر کہو، دیکھو کیاکہہ رہے ہو؟ صحابہ? نے عرض کیا: یارسول اللہ! ہم تو ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ ہم میں ہر شخص کو اپنا مال زیادہ محبوب ہے۔ حضورﷺ نے فرمایا: تم میں کوئی بھی ایسا نہیں جس کو اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ صحابہ نے عرض کیا: حضور! یہ کس طرح؟ حضورﷺ نے فرمایا: تمہارا مال و ہ ہے جو آگے بھیج دیا اوروارث کا مال و ہ ہے جوپیچھے چھوڑ گیا۔ (کنز العمال)
یہاں ایک بات یہ بھی قابلِ لحاظ ہے کہ ان روایات کا مقصد وارثوں کو محروم کرنا نہیں ہے۔ حضورِ اقدسﷺ نے خود اس پر تنبیہ فرمائی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ فتح مکہ کے زمانہ میں ایسے سخت بیمارہوئے کہ زِیست کی امید نہ رہی۔ حضورﷺ عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو انھوں نے عرض کیا کہ حضور! میرے پاس مال زیادہ ہے اور میری وارث صرف ایک بیٹی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اپنے سارے مال کی وصیت کروں (کہ اس وقت ان کی اولاد صرف ایک بیٹی ہی تھی اور اس کاتکفُّل اس کے خاوند کے ذمہ)۔ حضورﷺ نے منع فرما دیا۔ انھوں نے دو تہائی کی اجازت چاہی، حضورﷺ نے اس کا بھی انکار کر دیا۔ پھرنصف کی درخواست بھی قبول نہ فرمائی تو انھوں نے ایک تہائی وصیت کی اجازت چاہی۔ حضورﷺ نے اس کی اجازت فرما دی اور ارشاد فرمایا کہ ایک تہائی بھی بہت ہے۔ تم اپنے وارثوں کو (یعنی مرنے کے وقت جو بھی ہوں، چناںچہ اس واقعہ کے بعد اور بھی اولاد ہوگئی تھی) غنی چھوڑو یہ اس سے بہتر ہے کہ ان کو فقیر چھوڑو کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ جو خرچ اللہ کے واسطے کیا جائے وہ ثواب کا موجِب ہے، حتیٰ کہ اللہ کے لیے اگر ایک لقمہ بیوی کو دیا جائے تواس پر بھی اجر ہے۔ (مشکوۃ المصابیح عن الصحیحین)
حافظ ابنِ حجر ؒ فرماتے ہیں کہ حضرت سعدؓ کا یہ قصہ پہلی حدیث یعنی ’’تم میںسے کون ایسا ہے کہ اس کو وارث کا مال محبوب ہو‘‘ کے منافی نہیں، اس لیے کہ اس حدیث کا مقصد اپنی صحت اور ضرورت کے وقت میں صدقہ کرنے کی ترغیب ہے۔ اور حضرت سعد ؓ کے قصہ میں مرض الموت میںسارا یا اکثر حصہ مال کا وصیت کرنا مقصود ہے۔ (فتح الباری) بندۂ ناکارہ کے نزدیک صرف یہی نہیں، بلکہ وارثوں کو نقصان پہنچانے کے ارادہ سے وصیت کرنا موجِبِ عتاب و عقاب ہے۔ حضور ﷺ کا پاک ارشاد ہے کہ بعض مرد اور عورت اللہ کی فرماںبرداری میں ساٹھ سال گزارتے ہیں اور جب مرنے کا وقت آتا ہے تو وصیت میں نقصان پہنچاتے ہیں، جس کی وجہ سے جہنم کی آگ ان کے لیے ضروری ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کی تائید میں حضرت ابوہریرہؓ نے قرآنِ پاک کی آیت {مِنْ بَعْدِ وَصِیَّۃٍ یُّوْصٰی بِھَا اَوْ دَیْنٍ غَیْرَ مُضَارٍّ} (النساء :ع ۲) پڑھی، جس کا ترجمہ اور مطلب یہ ہے کہ اوپرکی آیت میں جو ورثہ کو تقسیمِ مال کی تفصیل بیان ہوئی ہے وہ وصیت کے بقدر مال نکالنے کے بعد ہے۔ اور اگر اس کے ذمہ قر ض ہے تو قرض کی مقدار بھی وضع کرنے کے بعد، اس حال میں کہ وصیت کرنے والا کسی وارث کو ضرر نہ پہنچائے۔
ایک حدیث میں ہے کہ جو کسی وارث کی میراث کوقطع کرے اللہ اس کی میراث کو جنت سے قطع کرے گا۔ (مشکاۃ المصابیح) لہٰذا ا س کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ وصیت اور اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے میں یہ ارادہ اور نیت ہرگز نہ ہو کہ کہیں فلاں وارث نہ بن جائے، بلکہ ارادہ اور نیت اپنی ضرورت کا پورا کرنا، اپنے لیے ذخیرہ بنانا ہو۔ آدمی کے ارادہ اور نیت کو عبادات میں بہت زیادہ دخل ہے۔ حضورﷺ کا پاک ارشاد جو بہت زیادہ مشہور ہے: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّیَّاتِکہ اعمال کامدار نیت اور ارادہ پرہے۔ نماز جیسی اہم عبادت اللہ کے واسطے پڑھی جائے تو کتنی زیادہ موجب ِاجر، موجب ِثواب، موجب ِقُربت کہ کوئی دوسری عبادت اس کے برابر نہیں۔ یہی چیز ریاکاری اور دکھاوے کے واسطے پڑھی جائے توشرکِ اصغر اور وبال بن جائے۔ اس لیے خالص نیت اللہ کی رضا اور اپنی ضروت میں کام آناہونا چاہیے جس کی بہترین صورت یہ ہے کہ اپنی زندگی میں، اپنی تندرستی میں، اس حالت میں جب کہ یہ بھی معلوم نہ ہو کہ میں پہلے مروںگا یا و ارث پہلے مرجائے گا،اور کون وارث ہوگا اورکون نہ ہوگا، ایسے وقت میں خرچ کرے اور خوب خرچ کرے، جتنا زیادہ سے زیادہ صدقہ کرسکتا ہے کرے۔ وصیت کرے، وقف کرے اور جن مواقعِ خیر میں زیادہ ثواب کی امید ہو ان کی فکرو جستجو میں رہے۔ یہ نہیں کہ اپنے وقت میں تو بخل کرے اور جب مرنے لگے تو سخی بن جائے، جیسا کہ حضورﷺ کا پاک ارشاد پہلی فصل کی احادیث میں نمبر(۵) پرگزر چکا کہ افضل صدقہ وہ ہے جو حالتِ صحت میں کیا جائے، نہ یہ کہ جب جان نکلنے لگے تو کہے کہ اتنا فلاں کا،اتنا فلاں کا، حالاںکہ مال فلاں کا (یعنی وارث کا) ہوگیا۔
خوب سمجھ لو! میں سب سے پہلے اپنے نفس کو نصیحت کرتا ہوں، اس کے بعد اپنے دوستوں کو کہ ساتھ جانے والا صرف وہی مال ہے جس کو اللہ کے بینک میں جمع کر دیا۔ اور جس کو جمع کرکے اور خوب زیادہ بڑھا کر چھوڑ دیا وہ اپنے کام میں نہیں آتا۔ بعد میں نہ کوئی ماں باپ یاد رکھتا ہے، نہ بیوی اولاد پوچھتے ہیں إِلاَّ مَا شَائَ اللّٰہُ۔ اپنا ہی کیا اپنے کام آتا ہے۔ ان سب کی ساری محبتوں کا خلاصہ دو چار دن ہائے ہائے کرنا ہے اور پانچ سات مفت کے آنسو بہانا ہے۔ اگر ان آنسوئوں میں بھی پیسے خرچ کرنا پڑیں تو یہ بھی نہ رہیں۔
یہ خیال کہ اولاد کی خیرخواہی سے مال کو جمع کرکے چھوڑنا ہے، نفس کا محض دھوکا ہے۔ صرف مال جمع کرکے ان کے لیے چھوڑ جانا، ان کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے، بلکہ شاید بدخواہی بن جائے۔ اگر واقعی اولاد کی خیر خواہی مقصود ہے، اگر واقعی یہ دل چاہتا ہے کہ وہ اپنے مرنے کے بعد پریشان حال، ذلیل و خوار نہ پھریں، تو ان کو مال دار چھوڑنے سے زیادہ ضروری ان کو دین دار چھوڑنا ہے کہ بددینی کے ساتھ مال بھی اوّلاً ان کے پاس باقی نہ رہے گا، چند یوم کی لذات و شہوات میں اڑ جائے گا اور اگر رہا بھی تو اپنے کسی کام کا نہیں ہے۔ اور دین داری کے ساتھ اگر مال نہ بھی ہو تو ان کی دین داری ان کے لیے بھی کام آنے والی چیز ہے اور اپنے لیے بھی کام آنے والی چیز ہے، اور مال میں سے تو اپنے کام آنے والا صرف وہی ہے جو ساتھ لے گیا۔
حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ شا نہٗ نے دو غنی اور دو فقیروں کو وفات دی۔ اس کے بعد ایک غنی سے مطالبہ فرمایا کہ اپنے واسطے آگے کیا بھیجا اور اپنے عیال کے واسطے کیا چھوڑ کر آیا؟ اس نے عرض کیا: یا اللہ! تُو نے مجھے بھی پیدا کیا اور ان کو بھی تُو نے ہی پیدا کیا، اور ہر شخص کی روزی کا تُو نے ہی ذمہ لیا اور تُو نے قرآنِ پاک میں فرمایا: {مَنْ ذَا الَّذِیْ یُقْرِضُ اللّٰہَ قَرْضًا حَسَنًا} (پہلی فصل کی آیات میں نمبر ۵ پرگزر چکی ہے) اس بنا پر میں نے اپنا مال آگے بھیج دیا اور مجھے یہ بات محقَّق تھی کہ آپ ان کوروزی دیں ہی گے۔ ارشاد ہوا: اچھا جائو، اگر تمہیں (دنیا میں) معلوم ہو جاتا کہ تمہارے لیے میرے پاس کیاکیا (انعام و اکرام ) ہے تو دنیا میں بہت خوش ہوتے اور بہت کم رنجیدہ ہوتے۔
اس کے بعد دوسرے غنی سے مطالبہ ہوا کہ تُو نے کیا اپنے لیے بھیجا اورکیا عیال کے لیے چھوڑا؟ اس نے عرض کیاـ: یا اللہ! میری اولاد تھی مجھے ان کی تکلیف اور فقرکا ڈر ہوا۔ ارشادہوا کہ کیا میں نے ہی تجھ کو اور ان کوسب کو پیدا نہ کیا تھا؟کیا میں نے سب کی روزی کا ذمہ نہیں اٹھایاتھا؟ اس نے عرض کیا: یا اللہ! بے شک ایسا ہی تھا، لیکن مجھے ان کے فقر کا خوف ہی بہت ہوا۔ ارشاد ہوا کہ فقرتو ان کوپہنچا، کیا تُونے اس کو ان سے روک دیا؟ اچھا جا، اگر تجھے (دنیا میں) معلوم ہو جاتا کہ تیرے لیے میرے پاس کیا کیا (عذاب) ہے تو بہت کم ہنستا اور بہت زیادہ روتا۔
پھر ایک فقیر سے مطالبہ ہوا کہ تُو نے کیا اپنے لیے جمع کیا اور کیا عیال کے لیے چھوڑا؟ اس نے عرض کیا: یا اللہ! آپ نے مجھے صحیح سالم تندرست پیدا کیا اور گویائی بخشی۔ اپنے پاک نام مجھے سکھائے۔ اپنے سے دعا کرنا سکھایا۔ اگر آپ مجھے مال دے دیتے تُو مجھے یہ اندیشہ تھا کہ میں اس میں مشغول ہوجاتا۔ میں اپنی اس حالت پر جو تھی بہت راضی ہوں۔ ارشاد ہوا کہ اچھا جاؤ، میں بھی تم سے راضی ہوں۔ اگر تمہیں (دنیا میں) معلوم ہوجاتا کہ تمہارے لیے میرے پاس کیا ہے تو بہت زیادہ ہنستے اور بہت کم روتے۔
پھردوسرے فقیر سے مطالبہ ہوا کہ تُو نے اپنے لیے کیابھیجا اور عیال کے لیے کیاچھوڑا؟ اس نے عرض کیا: یااللہ! آپ نے مجھے دیا ہی کیا تھا جس کا اب سوال ہے؟ ارشاد ہوا کیا ہم نے تجھے صحت نہ دی تھی، گویائی نہ دی تھی، کان، آنکھ نہ دیے تھے؟ اورقرآنِ پاک میں یہ نہ کہا تھا:
{اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ}
مجھ سے دعائیں مانگو میں قبول کروں گا اس نے عرض کیا: یا اللہ! یہ تو بے شک سب صحیح ہے، مگر مجھ سے بھول ہوئی۔ ارشاد ہوا کہ اچھا آج ہم نے بھی تجھے بھلا دیا۔ جاچلا جا، اگر تجھے خبر ہوتی کہ تیرے لیے ہمارے یہاں کیا کیا عذاب ہے تو بہت کم ہنستا اور بہت زیادہ روتا۔ (کنز العمال)
۱۰۔ عَنْ عُمَرَؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْجَالِبُ مَرْزُوْقٌ وَالْمُحْتَکِرُ مَلْعُوْنٌَ۔
رواہ ابن ماجۃ والدارمي، کذا في مشکاۃ المصابیح۔
حضرت عمرؓ حضورِ اقدسﷺ کاارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص رزق (غلہ وغیرہ) باہر سے لائے (تاکہ لوگوں کو اَرزاں دے ) اس کو روزی دی جاتی ہے اور جو شخص روک کر رکھے وہ ملعون ہے۔
فائدہ: فقیہ ابو اللیث سمر قندی ؒ فرماتے ہیں کہ باہر سے لانے والے سے وہ شخص مراد ہے جو تجارت کی غرض سے دوسرے شہروں سے غلہ خریدکرلائے تاکہ لوگوں کے ہاتھ اَرزاں فروخت کرے، تو اس کو (اللہ کی طرف سے) روزی دے جاتی ہے، کیوںکہ لوگ اس سے منتفع ہوتے ہیں، ان کی دعائیں اس کو لگتی ہیں۔ اور روکنے والے سے وہ شخص مرادہے جو روکنے کی نیت سے خریدکر رکھے اورلوگوں کو اس سے نقصان پہنچے۔ (تنبیہ الغافلین)
یعنی گرانی کے انتظار میںروکے رکھے اور باوجود لوگوں کی حاجت کے فروخت نہ کرے اس پرلعنت ہے۔ یعنی بخل اورلالچ اور نفع کمانے کی غرض سے غلہ وغیرہ جن چیزوں کی لوگوں کو اپنی زندگی کے لیے اِحتیاج ہے، خرید کر روکے رکھے اورگرانی کی زیادتی کا دن بہ دن انتظار کرتا رہے، اس پر حضورﷺ کی طرف سے لعنت کی گئی۔
ایک اور حدیث میں حضورﷺ کا ارشاد نقل کیاگیا کہ جو شخص مسلمانوں پر ان کے کھانے کو چالیس دن تک (باوجود سخت اِحتیاج کے) روکے ر کھے (فروخت نہ کرے) حق تعالیٰ شانہٗ اس کو کوڑھ کے مرض میں اور اِفلاس میں مبتلا کرتے ہیں۔ (مشکاۃ المصابیح) اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا ہے اور فقر میں مبتلا کرتا ہے، اس پر بدنی عذاب (کوڑھ) بھی مسلط ہوتا ہے اور مالی عذاب اِفلاس و فقر بھی۔ اور اس کے بالمقابل پہلی حدیث میں گزر چکا ہے کہ جو دوسری جگہ سے لاکر اَرزانی سے فروخت کرتا ہے اللہ خود اس کو روزی (اور نفع) پہنچاتے ہیں۔
ایک اور حدیث میں ہے کہ غلہ روکنے والا بھی کیسا برا آدمی ہے کہ اگر نرخ اَرزاں ہوتا ہے تو اس کو ر نج ہوتا ہے اور اگر گراں ہوتا ہے توخوش ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو چالیس دن اِحتیاج کے باوجود غلہ روکے رکھے (فروخت نہ کرے) پھر اس کو لوگوں پر صدقہ کر دے، تو یہ صدقہ کرنا بھی اس روکنے کا کفارہ نہ ہوگا۔ (مشکاۃ المصابیح) ایک حدیث میں آیا کہ پہلی اُمتوںمیں ایک بزرگ ریت کے ایک ٹیلہ پرکو گزرے۔ گرانی کا زمانہ تھا۔ وہ اپنے دل میں یہ تمنا کرنے لگے کہ اگر یہ ریت کا ٹیلہ غلہ کا ڈھیرہوتا تو میں اس سے بنی اسرائیل کو خوب کھلاتا۔ حق تعالیٰ شا نہٗ نے اس زمانہ کے نبی علیٰ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام پر وحی اِرسال کی کہ فلاں بزرگ کو بشارت سنا دو کہ ہم نے تمہارے لیے اتنا ہی اجرو ثواب لکھ دیا جتنا کہ یہ ٹیلہ غلہ کا ہوتا اور تم اس کو لوگوں میں تقسیم کر دیتے۔ (تنبیہ الغافلین)
حق تعالیٰ شا نہٗ کے یہاں ثواب کی کمی نہیںہے، اس کو اجر و ثواب دینے کے لیے نہ ذخیرہ کی ضرورت ہے، نہ آمدنی اورکمائی کی۔ اس کے ایک اشارہ میںساری دنیا کی پیداوار ہے۔ وہاں لوگوں کا عمل و اخلاص دیکھا جاتا ہے اور جو اس کی مخلوق پر رحمت و شفقت کرتا ہے، اس پر رحمت و شفقت میں وہاں کوئی کمی نہیں۔
حضرت عبد اللہ بن عباس?کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے کچھ نصیحت فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں چھ چیزوں کی نصیحت کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز اللہ پر بھروسہ اور یقین ان چیزوں کاجن کا اللہ نے خود ذمہ لے رکھاہے۔ (مثلًا روزی وغیرہ) دوسرے اللہ کے فرائض کو اپنے اپنے وقت پر ادا کرنا۔ تیسرے زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے ترو تازہ رہے۔ چوتھے شیطان کا کہا نہ ماننا، وہ ساری مخلوق سے حسد رکھتا ہے۔ پانچویں دنیا کے آباد کرنے میں مشغول نہ ہونا کہ وہ آخرت کو برباد کرے گی۔ چھٹے مسلمانوں کی خیر خواہی کا ہر وقت خیال رکھنا۔
فقیہ ابواللیث ؒ فرماتے ہیں کہ آدمی کی سعادت کی گیارہ علامتیں ہیں اور اس کی بدبختی کی بھی گیارہ علامات ہیں۔ سعادت کی گیارہ علامات یہ ہیں:
۱۔ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف رغبت کرنا۔ ۲۔ عبادت اور تلاوتِ قرآن کی کثرت۔ ۳۔ فضول بات سے اِحتراز۔ ۴۔ نمازکا اپنے اوقات پر خصوصی اہتمام۔ ۵۔ حرام چیز سے، چاہے ادنیٰ درجہ کی حرام ہو بچنا۔ ۶۔ صلحا کی صحبت اختیار کرنا۔ ۷۔ متواضع رہنا،تکبر نہ کرنا۔ ۸۔ سخی اور کریم ہونا۔ ۹۔ اللہ کی مخلوق پر شفقت کرنا۔ ۱۰۔ مخلوق کو نفع پہنچانا۔ ۱۱۔ موت کو کثرت سے یاد کرنا۔
اور بدبختی کی علامات یہ ہیں:
۱۔ مال کے جمع کرنے کی حرص۔ ۲۔ دنیوی لذتوں اور شہوتوں میں مشغولی۔ ۳۔ بے حیائی کی گفتگو اور بہت بولنا۔ ۴۔ نماز میں سستی کرنا۔ ۵۔حرام اور مشتبہ چیزوں کا کھانا اور فاسق فاجرلوگوں سے میل جول۔ ۶۔ بدخلق ہونا۔ ۷۔متکبر اور فخر کرنے والا ہونا۔ ۸۔ لوگوں کے نفع پہنچانے سے یکسو رہنا۔ ۹۔ مسلمانوں پر رحم نہ کرنا۔ ۱۰۔ بخیل ہونا۔ ۱۱۔ موت سے غافل ہونا ۔ (تنبیہ الغافلین)
بندۂ ناکارہ کے نزدیک ان سب کی جڑ موت کو کثرت سے یاد رکھنا ہے۔ جب وہ ہر وقت یاد آتی رہے گی تو پہلی گیارہ علامات ان شاء اللہ پیدا ہو جائیں گے اور دوسری گیارہ سے بچائو حاصل ہوجائے گا۔ حضورِ اقدسﷺ کا حکم ہے کہ لذتوں کی توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ (مشکاۃ المصابیح)
۱۱۔ عَنْ أَنَسٍؓ قَالَ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِّنَ الصَّحَابَۃِ فَقَالَ رَجُلٌ: أَبْشِرْ بِالْجَنَّۃِ۔ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ ﷺ: أَوَ لَا تَدْرِیْ لَعَلَّہُ تَکَلَّمَ فِیْمَا لَا یَعْنِیْہٖ، أَوْ بَخِلَ بِمَا لَا یَنْقُصُہُ۔
رواہ الترمذي، کذا في مشکاۃ المصابیح۔
حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کا انتقال ہوا تو مجمع میں سے کسی نے ان کو بظاہر حالات کے اعتبار سے جنتی بتایا۔ حضورﷺ نے فرمایا: تمہیں کیا خبر ہے، ممکن ہے کبھی انھوں نے بے کار بات زبان سے نکال دی ہو یا کبھی ایسی چیز میں بخل کیاہو جس سے ان کوکوئی نقصان نہیں پہنچتا تھا۔
فائدہ: یعنی یہ چیزیں بھی ابتداء ًاجنت میں جانے سے مانع بن جاتی ہیں۔ حالاںکہ بے کار باتوں میں منہمک رہنا اور فضول گفتگو میںاوقات ضائع کرنا ہم لوگوں کا ایسا دلچسپ مشغلہ ہے کہ شاید ہی کسی کی کوئی مجلس اس سے خالی ہوتی ہو، لیکن حضورِ اقدسﷺ کی شفقت اور رحمت علی الامت کے قربان کہ حضورﷺ نے ہر مشکل کا حل بتایا اور تیئس برس کے قلیل زمانہ میں ساری دنیا کی ہر قسم کی ضرورتوں کا حل تجویز فرمایا۔ حضورﷺ کا پاک ارشادہے کہ مجلس کا کفارہ یہ دعا ہے، مجلس ختم ہونے کے بعد اٹھنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کرے: سُبْحَانَ اللّٰہِ وَبِحَمْدِہٖ، سُبْحَانَکَ اللّٰھُمَّ وَبِحَمْدِکَ، أَشْھَدُ أَنْ لَا إِلٰـہَ إِلاَّ اَنْتَ، أَسْتَغْفِرُکَ وَأَتُوْبُ إِلَیک۔(حصن حصین)
دوسری چیز حدیثِ بالا میں وہی بخل ہے کہ شاید ایسی چیز میں بخل کرلیا ہو جس سے کوئی نقصان نہیں تھا۔ ایک اور حدیث میں یہ قصہ ذرا تفصیل سے آیا ہے۔ اس میں حضورﷺ کا ارشاد ہے کہ شاید کسی لایعنی چیز میں گفتگو کرلی ہو یا کسی لایعنی چیز میں بخل کرلیا ہو۔ (کنز العمال) ہم لوگ بہت سی چیزوں کو بہت سرسری سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں ثواب کے اعتبار سے بھی اور عذاب کے اعتبار سے بھی ان کا بہت اونچا درجہ ہوتا ہے۔ ’’بخاری شریف‘‘ کی ایک حدیث میں ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا کی کوئی بات زبان سے نکالتا ہے جس کو وہ کچھ اہم بھی نہیں سمجھتا، لیکن اس کی وجہ سے اس کے درجات بہت بلند ہو جاتے ہیں۔ اور کوئی کلمہ اللہ کی ناراضی کا کہہ دیتا ہے جس کی پرواہ بھی نہیں کرتا، لیکن اس کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ او ر ایک حدیث میںہے کہ اتنا نیچے پھینک دیا جاتا ہے جتنی مشرق سے مغرب دور ہے۔ (مشکوۃالمصابیح)
۱۲۔ عَنْ مَوْلًی لِّعُثْمَانَ قَالَ: أُھْدِيَ لِأُمِّ سَلَمَۃَ ؓ بِضْعَۃٌ مِّنْ لَحْمٍ وَکَانَ النَّبِيُّ ﷺ یُعْجِبُہُ اللَّحْمُّ، فَقَالَتْ لِلْخَادِمِ: ضَعِیْہِ فِيْ الْبَیْتِ لَعَلَّ النَّبِيَّ ﷺ یَاْکُلُہُ، فَوَضَعَتْہُ فِيْ کُوَّۃِ الْبَیْتِ وَجَائَ سَائِلٌ فَقَامَ عَلَی الْبَابِ فَقَالَ: تَصَدَّقُوْا بَارَکَ اللّٰہُ فِیْکُمْ! فَقَالُوْا: بَارَکَ اللّٰہُ فِیْکَ۔ فَذَھَبَ السَّائِلُ۔ فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: یَا أُمَّ سَلَمَۃَ! ھَلْ عِنْدَکُمْ شيئٌ أَطْعَمُہُ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ۔ قَالَتْ: لِلْخَادِمِ اِذْھَبِيْ فَأْتِيْ رَسُوْلَ اللّٰہِ ﷺ بِذٰلِکَ اللَّحْمِ۔ فَذَھْبَتْ فَلَمْ تَجِدْ فِيْالْکُوَّۃِ إِلاَّ قِطْعَۃَ مَرْوَۃٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: فَإِنَّ ذٰلِکَ اللَّحْمَ عَادَ مَرْوَۃً لِمَا لَمْ تُعْطُوْہُ السَّائِلَ۔
رواہ البیھقي في دلائل النبوۃ، کذا في مشکاۃ المصابیح۔
ام المؤمنین حضرت ام سلمہؓ کی خدمت میں کسی شخص نے گوشت کا ایک ٹکڑا (پکا ہوا) ہدیہ کے طور پر پیش کیا۔ چوںکہ حضورِاقدسﷺکو گوشت کا بہت شوق تھا اس لیے حضرت ام سلمہؓ نے خادمہ سے فرمایا کہ اس کو اندر رکھ دے شایدکسی وقت حضورﷺ نوش فرمالیں۔ خادمہ نے اس کو اندر طاق میں رکھ دیا۔ اس کے بعد ایک سائل آیا اور دروازے پر کھڑے ہو کر سوال کیا کہ کچھ اللہ کے واسطے دے دو، اللہ تمہارے یہاں برکت فرمائے۔ گھر میں سے جواب ملا کہ اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے۔ (یہ اشارہ تھا کہ کوئی چیز دینے کے لیے موجود نہیں) وہ سائل تو چلاگیا اتنے میں حضورِاقدسﷺ تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ ام سلمہ! میں کچھ کھانا چاہتا ہوں، کوئی چیز تمہارے یہاں ہے؟
حضرت ام سلمہؓ نے خادمہ سے فرمایا کہ جائووہ گوشت حضورﷺکی خدمت میں پیش کرو۔ وہ اندر گئیں اور جاکر دیکھا کہ طاق میں گوشت تو ہے نہیں، سفیدپتھر کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا ہے۔ (حضورِ اقدسﷺکو واقعہ معلوم ہوا تو) حضورﷺ نے فرمایا: تم نے وہ گوشت چوںکہ سائل (فقیر) کو نہ دیا اس لیے وہ گوشت پتھر کا ٹکڑا بن گیا۔
فائدہ: بڑی عبرت کامقام ہے۔ ازواجِ مطہرّات کی سخاوت اور فیاضی کا کوئی کیامقابلہ کرسکتا ہے۔ ایک ٹکڑا گوشت کا اگر انھوں نے ضرورت سے روک لیا اور وہ بھی اپنی ضرورت سے نہیں بلکہ حضورِاقدسﷺ کی ضرورت سے روکا، تواس کا یہ حشر ہوا۔ اور یہ بھی حقیقتاً اللہ کا خاص لطف وکرم حضورﷺ کے گھر والوں کے ساتھ تھا کہ اس گوشت کا جو اثر فقیر کو نہ دینے سے ہوا، وہ حضورﷺ کی برکت سے اپنی اصلی حالت میںگھروالوں پر ظاہرہوگیا،جس کا مطلب یہ ہوا کہ ضرورت مند سے بچاکر اور انکار کرکے جو شخص کھاتا ہے وہ اثر اور ثمرہ کے اعتبار سے ایسا ہے جیسا کہ پتھر کھالیا ہو کہ اس سے اس چیز کا اصل فائدہ حاصل نہ ہوگا، بلکہ سخت دلی اور منافع سے محرومی حاصل ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ بہت سی اللہ تعالیٰ شا نہٗ کی نعمتیں کھاتے ہیں، لیکن ان سے وہ فوائد بہت کم حاصل ہوتے ہیں جو ہونے چاہئیں اورکہتے ہیں کہ چیزوں میں اثر نہیں رہا۔ حالاںکہ حقیقت میں اپنی نیتیں خرا ب ہیں اس لیے بدنیتی سے فوائد میں کمی ہوتی ہے۔
۱۳۔ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِیْہِ عَنْ جَدِّہٖ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أَوَّلُ صَلَاحِ ھٰذِہِ الْأُمَّۃِ الْیَقِیْنُ وَالزُّھْدُ، وَأَوَّلُ فَسَادِھَا الْبُخْلُ وَالْأَمَلُ۔
رواہ البیھقي في الشعب، کذا في مشکاۃ المصابیح۔
حضورِ اقد سﷺ کاپاک ارشاد ہے کہ اس امت کی صلاح کی ابتدا (اللہ تعالیٰ کے ساتھ) یقین اور دنیا سے بے رغبتی سے ہوئی اور اس کے فساد کی ابتدا بخل اور لمبی لمبی امیدوں سے (ہوگی)۔
فائدہ: حقیقت میں بخل بھی لمبی لمبی امیدوں سے ہی پیدا ہوتا ہے کہ آدمی دور دور کے منصوبے سوچتا ہے پھر اس کے لیے جمع کرنے کی فکر ہوتی ہے۔ اگر آدمی کو اپنی موت یاد آتی رہے اور یہ سوچتا رہے کہ نہ معلوم کے دن کی زندگی ہے، تو پھر نہ تو زیادہ دور کی سوچ و فکر ہو، نہ زیادہ جمع کرنے کی ضرورت ہو، بلکہ اگر موت یاد آتی رہے تو پھر اُس گھرکے لیے زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی فکر ہر وقت سوار رہے۔
۱۴۔ عَنْ اَبِيْ ھُرَیْرَۃَ ؓ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَی بِلَالٍ وَ عِنْدَہُ صُبْرَۃٌ مِّنْ تَمَرٍ، فَقَالَ: مَا ھٰذَا یَا بِلَالُ؟ قَالَ: شَيْئٌ اِدَّخَرْتُہُ لِغَدٍ۔ فَقَالَ: أَمَا تَخْشَی أَنْ تَرَی لَہُ غَدًا بُخَارًا فِيْ نَارِجَھَنَّمَ؟ أَنْفِقْ یَا بَلَالُ! وَلَا تَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْلاَلاً۔
رواہ البیھقي في الشعب، کذا في مشکاۃ المصابیح۔
حضورِاقدسﷺ ایک مرتبہ حضرت بلالؓ کے پاس داخل ہوئے توان کے سامنے کھجوروں کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا۔ حضور ﷺ نے دریافت فرمایا کہ بلال! یہ کیا ہے؟ انھوں نے عرض کیا: حضور آیندہ کی ضروریات کے لیے ذخیرہ کے طور پر رکھ لیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ بلال! تم اس سے نہیں ڈرتے کہ اس کی وجہ سے کل کو قیامت کے دن جہنم کی آگ کا دھواں تم
دیکھو؟ بلال! خرچ کر ڈالو اور عرش والے () سے کمی کا خوف نہ کرو۔
فائدہ: ہرشخص کی ایک شان اور ایک حالت ہوا کرتی ہے۔ ہم جیسے کمزور، ضعفا، ضعیف الایمان، ضعیف الیقین لوگوں کے لیے شرعا اس کی گنجایش ہو بھی کہ وہ ذخیرہ کے طور پر آیندہ کی ضروریات کے لیے کچھ رکھ لیں، لیکن حضرت بلال ؓ جیسے جلیل القدر، کامل الایمان، کامل الیقین کی یہی شان تھی کہ ان کو اللہ سے کمی کا ذرا بھی خوف یا واہمہ نہ ہو۔ جہنم کا دھواںدیکھنے سے اس میں جانا لازم نہیں آتا، لیکن ان لوگوں کے اعتبار سے کمی تو ضرور ہوگئی جن کو یہ بھی نظر نہ آئے اورکم سے کم حساب کاقصہ تو لمبا ہو ہی جائے گا۔ بعض احادیث میں معمولی معمولی رقم ایک دو دینار کسی شخص کے پاس نکلنے پر بھی حضورِاقدسﷺ کی طرف سے جہنم کی آگ کی وعید وارد ہوئی ہے، جیسا کہ چھٹی فصل کی احادیث کے سلسلہ میں نمبر(۲) کے ذیل میں آرہا ہے۔ اور حساب کا معاملہ توہر شخص کے لیے ہے کہ جتنا مال زیادہ ہوگا اتنا ہی حساب طویل ہوگا۔ حضورﷺ کا پاک ارشادہے کہ میں جنت کے دروازہ پر کھڑا ہوا۔ میں نے دیکھا کہ اس میں کثرت سے داخل ہونے والے فقرا ہیں اور وسعت والے ابھی روکے ہوئے ہیں اور جہنمی لوگوں کو جہنم میں پھینک دیا گیا۔ اور میں جہنم کے دروازہ پر کھڑاہوا تو میں نے اس میں کثرت سے داخل ہونے والی عورتیں دیکھیں۔ (مشکاۃ المصابیح)
عورتوں کے جہنم میں کثرت سے داخل ہونے کی وجہ ایک اور حدیث میں آئی ہے۔ حضرت ابوسعیدؓ فرماتے ہیں کہ حضورِ اقدسﷺ عید کے دن عیدگاہ میں تشریف لے گئے۔ جب عورتوں کے مجمع پر گزر ہوا تو حضورﷺ نے عورتوں سے خطاب فرماکر ارشاد فرمایا کہ تم صدقہ بہت کثرت سے کیا کرو۔ میں نے عورتوں کو بہت کثرت سے جہنم میں دیکھا ہے۔ انھوں نے دریافت کیا: یا رسول اللہ! یہ کیا بات ہے؟ حضورﷺ نے فرمایا کہ عورتیں لعنت (بد دعائیں) بہت کرتی ہیں اور خاوند کی ناشکری بہت کرتی ہیں۔ (مشکاۃ المصابیح)
اور یہ دونوں باتیں عورتوں میں ایسی کثرت سے شائع ہیں کہ حد نہیں۔ جس اولاد پر دَم دیتی ہیں، ہر وقت اس کی راحت اور آرام کی فکر میںرہتی ہیں، ذرا ذرا سی بات پر اس کو ہر وقت بددعائیں، تُو مرجا، تُوگڑجا، تیرا ناس ہو جائے وغیرہ وغیرہ الفاظ ان کاتکیہ کلام ہوتا ہے۔ اور خاوند کی ناشکری کا تو پوچھنا ہی کیا ہے۔ وہ غریب جتنی بھی ناز برداری کرتا رہے ان کی نگاہ میں وہ لاپرواہ ہی رہتا ہے۔ ہر وقت اس غم میں مری رہتی ہیں کہ اس نے ماں کو کوئی چیز کیوں دے دی، باپ کو تنخواہ میں سے کچھ کیوں دے دیا، بہن بھائی سے سلوک کیوں کر دیا؟
ایک اور حدیث میں ہے کہ حضورﷺ نے صلوٰۃ الکسوف میں دوزخ جنت کا مشاہدہ فرمایا تو دوزخ میں کثرت سے عورتوں کو دیکھا۔ صحابہ? نے جب اس کی وجہ دریافت کی تو حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ وہ احسان فراموشی کرتی ہیں، خاوند کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر تُو تمام عمر ان میں سے کسی پر احسان کرتا رہے پھر کوئی ذرا سی بات پیش آجائے، توکہنے لگتی ہیں کہ میں نے تجھ سے کبھی کوئی بھلائی نہ دیکھی۔ (مشکاۃ المصابیح عن المتفق علیہ)
حضورﷺ کایہ ارشاد بھی عورتوں کی عام عادت ہے۔ جتنا بھی ان کے ساتھ اچھا برتائو کیا جائے، اگر کسی وقت کوئی بات ان کے خلافِ طبع پیش آجائے تو خاوند کے عمر بھر کے احسان سب ضائع ہو کر ’’اس گھروے میں مجھے کبھی چین نہ ملا ‘‘ ان کا خاص تکیہ کلام ہے۔ ان روایات سے عورتوں کے کثرت سے جہنم میں داخل ہونے کی وجہ معلوم ہونے کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اس سے بچائو اور حفاظت کی چیز بھی صدقہ کی کثرت ہے۔ چناںچہ اس وعید والی حدیث میں ہے کہ حضورﷺ جب یہ ارشاد فرما رہے تھے تو حضرت بلالؓ حضورﷺ کے ساتھ تھے اور صحابی عورتیں کثرت سے حضورﷺ کا پاک ارشاد سننے کے بعد اپنے کانوں کا زیور اور گلے کا زیور نکال نکال کر حضرت بلالؓ کے کپڑ ے میں جس میں وہ چند ہ جمع کررہے تھے ڈال رہی تھیں۔
ہمارے زمانہ میں اوّل توعورتوں کو اس قسم کی سخت حدیثیں سن کر خیال بھی نہیں ہوتا، اور اگر کسی کو ہوتا بھی ہے توپھر اس کا نزلہ بھی خاوند ہی پرگرتا ہے کہ وہ ہی ان کی زکوٰۃ ادا کرے، ان کی طرف سے صدقے کرے ۔ اگر وہ خود بھی کریں گی تو خاوند ہی سے وصول کرکے۔ مجال ہے کہ ان کے زیوروں کو کوئی آنچ آجاوے۔ ویسے چاہے سارا ہی چوری ہو جاوے، کھویا جائے، یا بیاہ شادیوں اور لغو تقریبات میں گرو ی رکھ کر ہاتھ سے جاتارہے، مگر اس کو اپنی خوشی سے اللہ کے یہاںجمع کرنا، اس کا کہیں ذکر نہیں۔ اسی حال میںاس کو چھوڑکر مر جاتی ہیں، پھر وہ وارثوں میں تقسیم ہو کر کم داموں میں فروخت ہوتا ہے۔ بنتے وقت نہایت گِراں بنتا ہے، بِکتے وقت نہایت اَرزاں جاتا ہے، لیکن ان کو اس سے کچھ غرض نہیں کہ یہ گھڑائی کے دام بالکل ضائع جارہے ہیں۔ ان کو بنواتے رہنے سے غرض۔ یہ تُڑوا کر وہ بنوالیا، وہ تُڑوا کر یہ بنوالیا، اور اپنے کام آنے والا نہ وہ ہے نہ یہ ہے۔ اور بار بار تڑوانے میںمال کی اِضاعت کے علاوہ گھڑائی کی اجرت ضائع ہوتی رہتی ہے۔
یہ مضمون درمیان میں عورتوں کی کثرت سے جہنم میں جانے کی وجہ میں آگیا تھا، اصل مضمون تو یہ تھا کہ مال کی کثرت کچھ نہ کچھ رنگ تو لاتی ہی ہے حتیٰ کہ حضرات مہاجرین ? کے بارے میں حضورﷺ کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن فقرا مہاجرین اَغنیا سے چالیس سال قبل جنت کی طرف بڑھ جائیںگے۔ (مشکاۃ المصابیح) حالاںکہ ان حضرات کے اِیثار اور صدقات کی کثرت اور اخلاص کا نہ تو اندازہ کیا جاسکتا ہے نہ مقابلہ ہوسکتا ہے۔ ایک مرتبہ حضورﷺ نے یہ دعا کی:
اَللّٰھُمَّ أَحْیِِنِيْ مِسْکِیْنًا وَّأَمِتْنِيْ مِسْکِیْنًا وَّاحْشُرْنِيْ فِيْ زُمْرَۃِ الْمَسَاکِیْنِ۔
اے اللہ! زندگی میں بھی مجھے مسکین رکھ اورمسکینی کی حالت میں مجھے موت عطا کر اور میرا حشر بھی مسکینوں کی جماعت میں فرما
حضرت عائشہؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ کیوں؟ یعنی آپ مسکینی کی دعاکیوں فرماتے ہیں؟ حضورﷺنے فرمایا کہ مساکین اپنے اَغنیا سے چالیس سال قبل جنت میں جائیں گے۔ عائشہ! مسکین کو نامراد واپس نہ کرو، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ عائشہ !مساکین سے محبت رکھا کرو، ان کو اپنا مقرب بنایا کرو، اللہ قیامت کے دن تمہیں اپنا مقرب بنائیں گے۔ (مشکاۃ المصابیح)
بعض علماء کو اس حدیث پر یہ اِشکال ہوگیا کہ اس سے عام فقرا کا اَنبیا سے مقدم ہونا لازم آتا ہے۔ بندہ کے ناقص خیال میں یہ اِشکال نہیں ہے۔ اس حدیث پاک میں اپنے اَغنیا کا لفظ موجود ہے ہر جماعت کے فقرا کا اس جماعت کے اَغنیا سے مقابلہ ہے۔ اَنبیا کا اَنبیا سے، صحابہ کا صحابہ سے اوراسی طرح اور جماعتیں۔
۱۵۔ عَنْ کَعْبِ بْنِ عِیَاضٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰہِ ﷺ یَقُوْلُ: إِنَّ لِکُلِّ اُمَّۃٍ فِتْنَۃً، وَفِتْنَۃُ اُمَّتِيْ الْمَالُ۔
رواہ الترمذي، کذا في مشکاۃ المصابیح۔
حضرت کعبؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضورِاقدسﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے (جس میں مبتلا ہو کر وہ فتنہ میں پڑجاتی ہے) میری امت کا فتنہ مال ہے۔
فائدہ: حضورِ اقدسﷺ کا پاک ارشاد بالکل ہی حق ہے، کوئی اِعتقادی چیز نہیں ہے۔ روز مرّہ کے مشاہدہ کی چیز ہے کہ مال کی کثرت سے جتنی آوارگی، عیاشی، سود خواری، زنا کاری، سینما بینی، جوا بازی، ظلم وستم، لوگوں کو حقیر سمجھنا، اللہ کے دین سے غافل ہونا، عبادات میں تساہُل، دین کے کاموں کے لیے وقت نہ ملنا وغیرہ وغیرہ ہوتے ہیں، ناداری میں ان کا تہائی چوتھائی بلکہ دسواں حصہ بھی نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے ایک مثل مشہور ہے ’’زَر نیست عشق ٹیں ٹیں‘‘ پیسہ پاس نہ ہو تو پھربازاری عشق بھی زبانی جمع خرچ ہی رہ جاتا ہے۔ اور یہ چیزیں نہ بھی ہوں تو کم سے کم درجہ مال کی بڑھوتری کا ہر وقت فکر تو کہیں گیا ہی نہیں۔ صرف تین ہزار روپیہ کسی کو دے دیجیے، پھر جو ہر وقت اس کو کسی کام میں لگا کر بڑھانے کا فکر دامن گیرہو گا تو کہاں کا سونا، کہاں کا راحت آرام، کیسا نماز روزہ، کیسا حج زکوٰۃ؟ اب دن بھر، رات بھر دکان کے بڑھانے کی فکر ہے۔ دکان کی مشغولی نہ کسی دینی کام میں شرکت کی اجازت دیتی ہے، نہ دین کے لیے کہیں باہر جانے کا وقت ملتا ہے کہ دکان کا حرج ہو جائے گا۔ ہر وقت یہ فکر سوار کہ کون سا کاروبار ایسا ہے جس میں نفع زیادہ ہو کام چلتا ہوا ہو۔ اسی لیے حضورﷺ کا پاک ارشاد جو کئی حدیثوں میں آیا ہے کہ اگر کسی آدمی کے لیے دو وادیاں (دو جنگل) مال کے حاصل ہو جائیں تو وہ تیسری کی تلاش میں لگ جاتا ہے۔ آدمی کاپیٹ (قبرکی ) مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ (مشکاۃ المصابیح)
ایک حدیث میں ہے کہ اگر آدمی کے لیے ایک وادی مال کی ہو تو دوسری کوتلاش کرتا ہے اور دوہوں تو تیسری کو تلاش کرتا ہے۔ آدمی کاپیٹ مٹی کے سواکوئی اور چیز نہیں بھرتی۔ ایک حدیث میں ہے کہ آدمی کے لیے ایک جنگل کھجوروں کاہو تو دوسرے کی تمنا کرتاہے۔ اور دو ہوں تو تیسرے کی۔ اور اسی طرح تمنائیں کرتا رہتا ہے۔ اس کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھرتی۔ (کنز العمال) ایک حدیث میں ہے کہ اگر آدمی کو ایک وادی سونے کی دے دی جائے تووہ دوسری کوتلاش کرتا ہے۔ اور دو ہوں تو تیسری کو تلاش کرتا ہے۔ آدمی کاپیٹ مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھرسکتی۔ (بخاری)
مٹی سے بھرنے کا مطلب یہ ہے کہ قبر کی مٹی میں جاکر ہی وہ اپنی اس ھَلْ مِنْ مَّزِیْدکی خواہش سے رک سکتا ہے۔ دنیا میں رہتے رہتے تو ہر وقت اس پر اِضافہ اورزیادتی کی فکر رہتی ہے۔ ایک کارخانہ اچھی طرح چل رہا ہے، اس میں بقدرِضر ورت آمدنی ہو رہی ہے، کہیں کوئی دوسری چیز سامنے آگئی اس میںبھی اپنی ٹانگ اڑا دی۔ ایک سے دو ہو گئیں، دو سے تین ہوگئیں، غرض جتنی آمدنی بڑھتی جائے گی، اس کو مزید کاروبار میں لگانے کی فکر رہے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ اس پر قناعت کرکے کچھ وقت اللہ کی یاد میں مشغولی کا نکل آئے۔ اسی لیے حضورِاقدسﷺ نے دعا فرمائی ہے:
اَللّٰھُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوْتًا۔
(اے اللہ! میری اولاد کا رزق قُوت ہو) یعنی بقدرِ کفایت ہو، زائد ہو ہی نہیں جس کے چکر میں میری اولاد پھنس جائے۔
ایک حدیث میں حضورﷺ کاارشاد ہے کہ بہتری اور خوبی اس شخص کے لیے ہے جو اسلام عطا کیا گیا ہو اور اس کا رزق بقدرِ کفایت ہو اور اس پر قانع ہو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ کوئی فقیر یا غنی قیامت میں ایسا نہ ہوگا جواس کی تمنا کرتا ہو کہ دنیا میںاس کی روزی صرف قُوت (یعنی بقدرِکفایت) ہوتی۔ (اِحیاء العلوم)
’’بخاری شریف‘‘ کی حدیث میں ہے حضورِاقدسﷺ کا ارشاد ہے کہ خدا کی قسم! مجھے تمہارے اوپر تمہارے فقرو فاقہ کا خوف نہیں ہے، بلکہ اس کا خوف ہے کہ تم پر دنیا کی وسعت ہوجائے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر ہو چکی ہے، پھر تمہارا اس میں دل لگنے لگے جیسا کہ ان کا لگنے لگا تھا، پس یہ چیز تمہیں بھی ہلاک کر دے جیسا کہ پہلی امتوں کو کرچکی ہے۔ (مشکاۃ المصابیح)
ان کے علاوہ اور بھی بہت سی روایات میں مختلف عنوانات سے مختلف قسم کی تنبیہات سے مال کی کثرت اور اس کے فتنہ پرمتنبہ فرمایا۔ اس لیے نہیںکہ مال في حدّ ذاتہٖ کوئی ناپاک یا عیب کی چیز ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ ہم لوگو ں کے قلوب کے فساد کی وجہ سے بہت جلد ہمارے دلوںمیں مال کی وجہ سے تعفّن اور بیماریاں پیدا ہوجاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص اس کی مضرتوں سے بچتے ہوئے، اس کی زیادتی سے اِحتراز کرتے ہوئے، شرائط کے ساتھ اس کو استعمال کرے تو مضر نہیں بلکہ مفید ہو جاتا ہے، لیکن چوںکہ عام طور سے نہ شرائط کی رعایت ہوتی ہے نہ اصلاح کی فکرہوتی ہے، اس بنا پر یہ اپنا زہریلا اثر بہت جلد پیدا کر دیتا ہے۔
اس کی بہترین مثال ہیضہ کے زمانہ میں امرود کا کھانا ہے کہ في حدّ ذاتہٖ امرود کے اندر کوئی عیب نہیں، اس کے جو فوائد ہیں وہ اب بھی اس میں موجود ہیں، لیکن ہوا کے فساد کی وجہ سے اس کے استعمال سے، بالخصوص کثرتِ استعمال سے بہت جلد اس میں تغیر پیدا ہوکر مضرت اور ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے علی العموم ڈاکٹر ہیضہ کے زمانہ میں امرودوں کی سختی سے ممانعت کر دیتے ہیں۔ ٹوکرے کے ٹوکرے ضائع کرا دیتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ اگر معمولی حکیم یا ڈاکٹرکسی چیز کو مضر بتاتا ہے توطبعاً ہمارے قلوب اس سے ڈرنے لگتے ہیں۔ چناںچہ ڈاکٹروں کے ان اعلانات کے بعد اچھے اچھے سورمائوں کی ہمت امرود کھانے کی نہیں رہتی، لیکن وہ ہستی جس کے جوتوںکی خاک تک بھی کوئی حکیم یا ڈاکٹر نہیں پہنچ سکتا، جس کی تجویزات نورِ نبوت سے مستفاد ہیں، اس کے اعلان پر، اس کی تجویز پر ذرا بھی خوف پیدا نہ ہو۔ حضورِ اقدسﷺ جب بار بار اس کے فتنوں اور اس کی مضرتوں پر تنبیہ فرمارہے ہیں تو یقینا ہر شخص کو بہت زیادہ اس کی مضرتوں سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اس کے استعمال کے لیے شرعی قوانین کے ماتحت جو اس کے لیے ایسے ہیں جیسا کہ امرود کے لیے نمک، مرچ، لیموں وغیرہ مُصلِحات ہیں، ان کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے حقوق کی ادائیگی کابہت زیادہ اس میں فکر کرتے رہنا چاہیے۔ خود حضورﷺ کا ارشاد ہے کہ غنیٰ میں اس شخص کے لیے نقصان نہیں جو اللہ سے ڈرتا رہے۔ (مشکاۃ المصابیح)
میرے نسبی بزرگوں میں مفتی الٰہی بخش کاندھلوی، مشہور فقیہ حضرتِ اقدس مرجع الکل شاہ عبدالعزیز دہلوی نور اللہ مرقدہ کے خاص شاگردہیں۔ ان کی بیا ض میں اُن کے شیخ کی بیاض سے نقل کیا ہے کہ دنیا (یعنی مال) آدمی کے لیے حق تعالیٰ شا نہٗ کی مرضیات پر عمل کرنے کے لیے بہترین مدد ہے۔حضورِاقدسﷺ نے جب لوگوں کوحق تعالیٰ شا نہٗ کی طرف بلایا تو ان چیزوں کے چھوڑ دینے کا حکم نہیں فرمایا، بلکہ اسبابِ معیشت اوراہل و عیال کی خدمت کی ترغیب دی۔ لہٰذا مال کا اور اپنے اہل و عیال میںرہنے کا انکار ناواقف شخص ہی کرسکتا ہے۔ حضرت عثمانؓ کے وصال کے وقت ان کے خزانچی کے پاس ایک لاکھ پچاس اشرفیاں او ر دس لاکھ درہم تھے، اور جائیداد خیبر، وادیٔ قریٰ وغیرہ کی تھی، جس کی قیمت دو لاکھ دینار تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر? کے مال کی قیمت پچاس ہزار دینار تھی اور ایک ہزار گھوڑے اور ایک ہزار غلام چھوڑے تھے۔ اور عمرو بن العاصؓ نے تین لاکھ دینار چھوڑے تھے۔ اور حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کے مال کا توشمار ہی مشکل ہے۔ اس کے باوجود حق تعالیٰ شا نہٗ نے ان کی تعریف قرآن پاک میں فرمائی:
{ یَدْعُوْنَ رَبَّھُمْ بِالْغَدَاۃِ وَالْعَشِیِّ یُرِیْدُوْنَ وَجْھَہٗ }(الکہف:ع ۴)
’’اپنے رب کی عبادت صبح و شام (یعنی ہمیشہ) محض اس کی ر ضا جوئی کے واسطے کرتے ہیں۔‘‘
اور ارشاد ہے۔
{رِجَالٌ لاَّ تُلْھِیْھِمْ تِجَارَۃٌ وَّلَابَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللّٰہِ} (النور:ع ۵)
’’یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو تجارت وغیرہ اللہ کے ذکر سے نہیںروکتی۔‘‘ فقطبیاض کی عبارت عربی ہے یہ اس کاترجمہ ہے۔ اور صحیح ہے کہ اس زمانہ میں فتوحات کی کثرت سے عام طور پر ان حضرات کی مالی حالت ایسی ہی تھی۔ دنیا اور ثروت ان کے جوتوں سے لپٹتی تھی یہ اس کو پھینکتے تھے اور وہ ان کو چمٹتی تھی، لیکن ان سب کے باوجود اس کے ساتھ اس کی دل بستگی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغولی کیا تھی۔ ’’ فضائل نماز ‘‘ اور ’’حکایاتِ صحابہ‘‘ میں ان حضرات کے کچھ واقعات ذکر کیے گئے ہیں، ان کو عبرت اور غور سے دیکھو۔ یہی عبداللہ بن زبیر? اپنی اس دولت کے ساتھ جب نماز کو کھڑے ہوتے تو جیسے ایک کیل کہیں گاڑ دی ہو۔ سجدہ اتنا لمبا ہوتا کہ چڑیاں کمر پر آکر بیٹھ جاتیں اور حرکت کا ذکر نہیں۔ جس زمانہ میں ان پر چڑھائی ہو رہی ہوتی اور ان پرگولہ باری ہو رہی تھی، نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک گولہ مسجد کی دیوار پرلگا جس سے اس کاایک حصہ گرا۔ ان کی داڑھی کے پاس سے گزرا، مگر ان کو اس کا پتہ بھی نہ چلا۔
ایک صحابی کاباغ کھجوروں کا خوب پک رہا تھا۔ یہ اس باغ میںنماز پڑھ رہے تھے۔ نماز میں باغ کا خیال آگیا اس کا رنج اور صدمہ اس قدر ہوا کہ نماز کے بعد فوراً باغ کو حضرت عثمان ؓ کی خدمت میں، جو اس وقت امیر المؤمنین تھے، پیش کر دیا۔ انھوں نے پچاس ہزار میںا س کو فروخت کرکے اس کی قیمت دینی کاموں میں خرچ کر دی۔ حضرت عائشہؓ کی خدمت میں دوبوریاں دِرَم کی نذرانہ میں آئیں جن میں ایک لاکھ سے زیادہ دِرَم تھے۔ طباق منگا کر اور بھر بھر کر سب تقسیم کر دیں۔ اپنا روزہ تھا یہ بھی خیال نہ آیاکہ اپنے افطار کے لیے کچھ رکھ لیں یا کوئی چیز منگا لیں۔ افطار کے وقت جب باندی نے افسوس کیا کہ اگر ایک دِرَم کا گوشت منگا لیتیں تو آج ہم بھی گوشت سے کھانا کھالیتے، تو فرمایا: اب افسوس سے کیا ہوتا ہے؟ جب یاد دلا دیتی تو میں منگا دیتی۔
’’حکایاتِ صحابہ‘‘ میں یہ اور اس قسم کے چند واقعات ذکر کیے گئے۔ ان کے علاوہ ہزاروں واقعات ان حضرات کی تاریخ میں موجود ہیں۔ اُن کو مال کیا نقصان دے سکتا ہے جن کے نزدیک اس میں اور گھر کے کوڑے میں کوئی فرق ہی نہ ہو۔ کاش! اللہ اس صفت کا کوئی شمّہ اس ناپاک کو بھی عطا کر دیتا۔
یہاں ایک بات خاص طور سے قابلِ لحاظ ہے۔ وہ یہ کہ ان حضرات متمول صحابہ کرام? کے ان احوال سے مال کی کثرت کے جواز پر استدلال تو ہوسکتا ہے کہ خیرالقرون اور خلفائے راشدین?کے دور میںیہ مثالیں بھی ملتی ہیں، لیکن ہم لوگوں کو اس زہر کے اپنے پاس رکھنے میں ان کے اِتباع کو آڑ بنانا ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی تپِ دق کابیمار کسی جوان، قوی، تندرست کے اِتباع میںروزانہ صحبت کیا کرے کہ وہ تین چار دن میں قبر کا گڑھا ہی دیکھے گا۔ رسالہ کے ختم پر حکایات کے سلسلہ میں نمبر (۵۴) پر ایک عارف کا ارشاد غور سے دیکھنا چاہیے۔ امام غزالی ؒ فرماتے ہیں کہ مال بہ منزلہ ایک سانپ کے ہے جس میں زہر بھی ہے اور تریاق بھی ہے۔ اور اس کے فوائدبہ منزلہ تریاق کے ہیں اور اس کے نقصانات بہ منزلہ زہر کے۔جو اس کے فوائد اور نقصانات سے واقف ہو جائے وہ اس پر قادر ہوسکتا ہے کہ اس کے فوائد حاصل کرے اور نقصانات سے محفوظ رہے۔ اس میں فوائد تو دو قسم کے ہیں دنیوی اور دینی۔ دنیوی فوائد توہر شخص جانتا ہے، انہی کی وجہ سے سارا جہان اس کے کمانے میں مرمٹ رہا ہے، دینی فوائد تین ہیں۔
اول یہ کہ بواسطہ یا بلاواسطہ عبادت کا سبب ہے۔ بلاواسطہ تو جیسے حج جہاد وغیرہ کہ یہ روپیہ ہی سے ہوسکتے ہیں، اور بواسطہ یہ کہ اپنے کھانے پینے اور ضروریات میں خرچ کرے کہ یہ ضرورتیں اگر پوری نہ ہوں تو آدمی کا دل ادھر مشغول رہتا ہے جس کی وجہ سے دینی مشاغل میں اِشتغال کاوقت نہیں ملتا۔ اور جب یہ بواسطہ عبادت کا ذریعہ ہے تو خود بھی عبادت ہوا، لیکن صرف اتنی ہی مقدار جس سے دینی مشاغل میں اِعانت ملے۔ اس سے زیادہ مقدار اس میں داخل نہیں۔
دوسرا دینی فائدہ اس سے کسی دوسرے پر خرچ کرنے کے متعلق ہے اور یہ چار قسم پر ہے۔ (الف) صدقہ جو غربا پر کیا جائے۔ اس کے فضائل بے شمار ہیں جیسا کہ پہلے کچھ گزر چکے۔ (ب) مروّت جو اَغنیا پر دعوت ہدیہ وغیرہ میں خرچ کیا جائے کہ وہ صدقہ نہیںہے، اس لیے کہ صدقہ فقرا پر ہوتا ہے۔ یہ قسم بھی دینی فوائد لیے ہوئے ہے کہ اس سے آپس کے تعلقات قوی ہوتے ہیں، سخاوت کی بہترین عبادت پیدا ہوتی ہے۔ بہت سی احادیث ہدایا اور کھانا کھلانے کے فضائل میں وارد ہوئی ہیں۔ اس قسم میںان لوگوں کے فقر کی قید نہیں ہے جن پر خرچ کیا جائے۔ (بندہ کے ناقص خیال میں یہ فائدہ بسا اوقات پہلے نمبر سے بھی بڑھ جاتا ہے، مگر جب ہی تو جب اس میں خرچ بھی کیا جائے، لیکن جو شخص ننانوے کے پھیر میں پڑ جائے اس کے لیے نہ یہ فضائل کارآمد ہیں، نہ وہ سب احادیث جو ان کے فضائل میں آئی ہیں اس پراثر کرتی ہیں۔ (ج) اپنی آبرو کاتحفظ۔ یعنی مال کا ایسی جگہ خرچ کرنا، جس میں اگر خرچ نہ کیا جائے تو کمینہ لوگوں کی طرف سے بدگوئی، فحش وغیرہ مضرتوں کا اندیشہ ہے۔ یہ بھی صدقہ کے حکم میں آتا ہے۔ حضورﷺ کا ارشاد ہے کہ آدمی اپنی آبرو کی حفاظت کے لیے جو خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ (بندۂ ناکارہ کے نزدیک دفعِ ظلم کے لیے رشوت دینا بھی اس میں داخل ہے۔ رشوت کا دینا کسی نفع کے حاصل کرنے کے واسطے حرام ہے ناجائز ہے۔ دینے والا بھی ایسا ہی گناہ گار ہے جیسا کہ لینے والا، لیکن ظالم کے ظلم کو ہٹانے کے واسطے دینے والے کوجائز ہے، لینے والے کو حرام ہے۔ (د) مزدوروں کی اجرت دینا کہ آدمی بہت سے کام خود اپنے ہاتھ سے نہیں کرسکتا۔ اور بعض کام ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو آدمی خود تو کرسکتا ہے، لیکن ان میں بہت سا عزیز وقت صرف ہوتا ہے۔ اگر ان کاموں کو اجرت پر کرالے تو اپنا یہ وقت علم و عمل، ذکر و فکر وغیرہ ایسے اُمور میں خرچ ہوسکتا ہے جن میں دوسرانائب نہیں ہوسکتا۔تیسرا دینی فائدہ عمومی اخراجاتِ خیر ہیں جن میں کسی دوسرے معیّن شخص پر توخرچ نہیں کیا جاتا کہ یہ دوسرے نمبر میںگزر چکے ہیں۔ البتہ عمومی فوائد اس سے حاصل ہوتے ہیں جیسا مساجد کا بنانا، مسافر خانے، پل وغیرہ بنانا، مدارس، شفا خانے وغیرہ ایسی چیزیں بنانا جواپنے مرنے کے بعد بھی ان کے اجر و ثواب اور ان سے فوائد حاصل کرنے والے صلحا کی دعائیں پہنچتی رہیں۔
یہ تو اِجمال ہے اس کے فوائد کا اور سارے فوائد جواس سے حاصل ہوسکتے ہیں وہ ان میںآگئے۔ حضرتِ اقدس شاہ عبدالعزیز صاحب قُدّس سرہٗ فرماتے ہیں کہ مال کا خرچ کرنا سات طرح سے عبادت ہے: ۱۔ زکوٰۃ جس میں عشر بھی داخل ہے۔ ۲۔ صدقۂ فطر۔ ۳۔ نفل خیرات جس میں مہمانی بھی داخل ہے اور قرض داروں کی اعانت بھی۔ ۴۔ وقف، مساجد، سرائے، پل وغیرہ بنانا۔ ۵۔ حج ،فرض ہو یا نفل، یا کسی دوسرے کی حج میںمدد ہو، توشہ سے یا سواری سے۔ ۶۔ جہاد میں خرچ کرنا کہ ایک دِرَم اس میں سا ت سو دِرَم کے برابر ہے۔ ۷۔جن کے اخراجات اپنے ذمہ ہیںان کو ادا کرنا، جیساکہ بیوی کااور چھوٹی اولاد کا خرچ ہے، اوراپنی وسعت کے بعد محتاج رشتہ داروں کا خرچ وغیرہ۔ (تفسیرِ عزیزی)
امام غزالی ؒفرماتے ہیں کہ مال کے نقصانات بھی دو قسم کے ہیں، دینی اور دنیوی۔ دینی نقصانات تین قسم پر ہیں:
(ا) معاصی کی کثرت کا سبب ہوتا ہے کہ آدمی اکثر و بیشتر اسی کی وجہ سے شہوتوں میںمبتلا ہوتا ہے، اور ناداری اور عجز ان کی طرف متوجہ بھی نہیں ہونے دیتا۔ جب آدمی کو کسی معصیت کے حصول سے ناامیدی ہوتی ہے تو دل اس طرف زیادہ متوجہ بھی نہیں ہوتا۔ اور جب اپنے کو اس پر قادر سمجھتا ہے تو کثرت سے ادھر توجہ رہتی ہے۔ اور مال قدرت کے بڑے اسباب میںسے ہے۔ اسی وجہ سے مال کا فتنہ فقر کے فتنے سے بڑھا ہوا ہے۔
(ب) جائز چیزوں میں تنعُّم کی کثرت کا سبب ہے۔ اچھے سے اچھا کھانا، اچھے سے اچھا لباس وغیرہ وغیرہ۔ بھلا مال دار سے یہ کب ہوسکتا ہے کہ جو کی روٹی کھائے اور موٹا کپڑا پہنے؟ اور ان تنعمات کا حال یہ ہے کہ ایک چیز دوسرے کو کھینچتی ہے اور شدہ شدہ اخراجات میںاضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اور آمدنی جب ان کو کافی نہیں ہوتی تو ناجائز طریقوں سے مال حاصل کرنے کی فکر یں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ اور جھوٹ نفاق وغیرہ بری عادات کی بنیاد اسی سے پڑتی ہے کہ ما ل کی کثرت کی وجہ سے ملاقاتی بھی کثیر ہوںگے، اور ان کے تعلقات کی بقا اور حفاظت کے واسطے اس قسم کے امور کثرت سے پیدا ہوں گے، اور تعلقات کی کثرت میں بغض وعداوت، حسد کینہ وغیرہ امور طرفین میںکثرت سے پیدا ہوںگے اور ایسے بے انتہا عوارض آدمی کیساتھ لگ جائیں گے جن سے مال کے ہوتے ہوئے خلاصی دشوار ہے۔ اور غور کرنے سے یہ مضرتیں وسیع پیمانے پر پہنچ جاتی ہیں اور ان سب کا پیدا ہونا مال ہی کے سبب سے ہوتا ہے۔
(ج) اور کم سے کم اس بات سے تو کوئی بھی مال دار خالی نہیں ہوسکتا کہ اس کا دل مال کی صلاح و فلاح کے خیال میںاللہ کے ذکر و فکر سے غافل رہے گا۔ اور جو چیز اللہ سے غافل کر دے وہ خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اسی واسطے حضرت عیسیٰ علیٰ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مال میں تین آفتیں ہیں۔ اول یہ کہ ناجائز طریقہ سے کمایا جاتا ہے۔ کسی نے عرض کیا کہ اگر جائز طریقہ سے حاصل ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ بے جگہ خرچ ہوتا ہے۔ کسی نے عرض کیا: اگر اپنے محل ہی پر خرچ کیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی اصلاح کافکر اللہ سے تو مشغول کرہی دے گا، اور یہ لاعلاج بیماری ہے کہ ساری عبادات کا لُبِ لباب اور مغز اللہ کا ذکر وفکر ہے اور اس کے لیے فارغ دل کی ضرورت ہے اور صاحب ِجائیداد شخص دن بھر، رات بھر کاشت کاروں کے جھگڑوں کے سوچ میں رہتا ہے، ان سے وصولی کے حساب کتاب میںرہتا ہے، شریکوں کے معاملات کی فکر میںرہتا ہے۔ کہیں ان کے حصول کا جھگڑا ہے، ان سے پانی کی بانٹ پر جھگڑا ہے،کہیں ڈول بندیوں پر لڑائی ہے، اور حکّام اور ان کے ایلچیوں کا قصہ علیحدہ ہر وقت کا ہے، نوکروں مزدوروں کی خبرگیری، ان کے کام کی نگرانی ایک مستقل مشغلہ ہے ۔ اسی طرح تاجر کا حال ہے کہ اگر شرکت میں تجارت ہو تو شرکا کی حرکتیں ہر وقت کی ایک مستقل مصیبت اور مستقل مشغلہ ہے۔ اور تنہا تجارت ہو تو نفع کے بڑھنے کا فکر، ہر وقت اپنی محنت میں کوتاہی کا خیال، تجارت میں نقصان کا فکر، ایسے امور ہیں جو ہر وقت مسلط رہتے ہیں۔ مشاغل کے اعتبار سے سب سے کم وہ خزانہ ہے جو نقد کی صورت میں اپنے پاس ہو، لیکن اس کی حفاظت اور اِضاعت کا اندیشہ، چوروں کا فکر اور اس کے خرچ کرنے کے مصارف کا فکر اور جن لوگوں کی نگاہیں اس کی طرف لگی رہتی ہیں ان کاخیال، ایسے تفکّرات ہیں کہ جن کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور یہی وہ سب دنیوی مضرات ہیں جومال کے ساتھ لگی رہتی ہیں اور جس کے پاس بقدرِ ضرورت ہو وہ ان سب افکار سے فارغ۔
لنگکے زیر لنگکے بالا
نے غم دُزد ، نے غم کالا
ایک لنگی نیچے ایک لنگی اوپر، نہ چور کا ڈر نہ پونجی کا۔
(کہ اس کی کس طرح حفاظت کروں، روز اَفزوں اخراجات کس طرح پورے کروں؟)
پس مال کا تریاق اس میں سے بقدرِ ضرورت اپنے ذاتی مصارف میں خرچ کرنے کے بعد جو کچھ بچے اس کو خیر کے مصارف میں خرچ کر دینا ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ زہر ہی زہر ہے،آفت ہی آفت ہے۔ حق تعالیٰ شا نہٗ اپنے لطف و کرم سے اس زہر سے اس ناکارہ کو بھی محفوظ رکھے اور نیک مصرف پر خرچ کی توفیق عطا فرمائے۔ (اِحیاء العلوم) اس کی مثال بالکل سانپ کی سی ہے کہ جو لوگ اس کے پکڑنے کے ماہر ہیں، اس کے طریقوں سے واقف ہیں، ان کے لیے اس کے پکڑنے میں کوئی نقصان نہیں،بلکہ وہ اس سے تریاق بنا سکتے ہیں اور دوسرے فوائد حاصل کرسکتے ہیں، لیکن کوئی ناواقف ان ماہروں کی حرص کرکے سانپ کو پکڑے گا تو ہلاک ہوگا۔ اسی طرح متمول صحابہ کرام ? کی حرص کرکے ہم لوگ اگر اس زہر کا استعمال کثرت سے کریں تو ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور ان حضراتِ کرام? کے متعلق محض اعتقادی بات نہیں، ان کی زندگی کا ایک ایک واقعہ اس کی کھلی شہادت دیتا ہے کہ ان کے یہاں اس کی وقعت ایندھن سے زیادہ نہ تھی۔ ان کے لیے اس کا وجود حق تعالیٰ شا نہٗ سے ذرا سی توجہ بھی ہٹانے والا نہ تھا اور اس کے باوجود اس سے ڈرتے تھے، جیسا کہ ان کی پوری تاریخ اس پر شاہد ہے۔
وَاللّٰہُ الْمُوَفِّقُ لِمَا یُحِبُّ وَیَرْضَی
تیسری فصل
صلۂ رِحمی کے بیان میں
یہ فصل درحقیقت پہلی ہی فصلوں کا تتمہ ہے، لیکن اللہ نے اپنے پاک کلام میں اور حضورﷺنے اپنے پاک ارشادات میں اس پر خصوصیت سے تاکیدیں فرمائی ہیں، اور تعلقات کے توڑنے پر خصوصی وعیدیں فرمائی ہیں۔ اس لیے اس مضمون کو اہتمام کی وجہ سے مستقل فصل میں ذکر کیا گیا۔ حضورِ اقدسﷺکا پاک ارشاد ہے کہ اہلِ قرابت پر صدقہ کا ثواب دوگنا ہے۔ (کنز العمال)
امّ المؤمنین حضرت میمونہؓ نے ایک باندی آزاد کی تو حضورﷺ نے فرمایا کہ اگر تم اس کو اپنے ماموئوں کو دے دیتیں تووہ افضل تھا۔ (کنز العمال) لہٰذا صدقات کے اندر اگرکوئی دوسری دینی ضرورت اہم نہ ہو تو عام صدقہ سے اہلِ قرابت پر صدقہ کرناا فضل ہے۔ البتہ اگر کوئی دینی ضرورت درپیش ہو تو اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے کا ثواب سات سو گنا تک ہو جاتا ہے۔ قرآنِ پاک میں اور احادیث میں بہت کثرت سے صلۂ رحمی کی ترغیبات اور قطع رحمی پر وعیدیں آئی ہیں، مگر خوف ہے اس رسالہ کے بڑھ جانے کا۔ اس لیے صرف تین آیات ترغیب کی اور تین آیات وعید کی ذکر کرکے چند احادیث اس مضمون کی ذکر کرتا ہوں کہ ذرا بھی طول ہوگیا توہم لوگوں کو ان کے پڑھنے کی بھی فرصت نہ ملے گی، مگر یہ سارے مضامین اس قدر اہم ہیں کہ باوجود اختصار کے بھی یہ رسالہ بڑھتا ہی جا رہا ہے اور ایک حصہ کے بجائے شاید دو حصے کرنے پڑ جائیں۔
۱۔ اِنَّ اللَّہَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِیْتَآئِ ذِی الْقُرْبٰی وَیَنْھٰی عَنِ الْفَحْشَآئِ وَالْمُنْکَرِ وَالْبَغْیِج یَعِظُکُمْ بے شک اللہ اعتدال کا اور احسان کا اور اہلِ قرابت کو دینے کا حکم فرماتے ہیں، اور منع کرتے ہیں بے حیائی سے اوربری
لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُوْنَ o (النحل :ع ۱۳)
بات سے اور کسی پر ظلم کرنے سے، اور تم کو
(ان امور کی) نصیحت فرماتے ہیں تاکہ تم نصیحت قبول کرلو۔
فائدہ: حق تعالیٰ شا نہٗ نے قرآنِ پاک میں بہت سی جگہ اہلِ قرابت کی خیر خواہی ، ان کو دینے کا حکم اور اس کی ترغیب فرمائی ہے۔ چند آیات کی طرف یہاں اشارہ کیا جاتا ہے ، جس کا دل چاہے کسی مترجم قرآن شریف کو لے کر دیکھ لے:
۱۔ وَبِالْوَالِدَیْنِ اِحْسَانًا وَّذِی الْقُرْبٰی (البقرۃ :ع ۱۰)
۲۔ قُلْ مَا اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَیْرٍ فَلِلْوَالِدَیْنِ وَالْاَقْرَبِیْنَ (البقرۃ : ع ۲۶)
۳۔ سورہ ٔنساء کا پہلا رکوع تمام ۔
۴۔ وَبِالْوَالِدَیْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِی الْقُرْبٰی (النساء:ع ۶)
۵۔ وَبِالْوَالِدَیْنِ اِحْسَانًاج (الأنعام: ع ۱۹)
۶۔ وَاُوْلُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُھُمْ اَوْلٰی بِبَعْضٍ فِیْ کِتَابِ اللّٰہِط (الأنفال: ع ۱۰)
۷۔ لَا تَثْرِیْبَ عَلَیْکُمُ الْیَوْمَ یَغْفِرُ اللّٰہُ لَکُمْز (یوسف: ع ۱۰)
۸۔ وَالَّذِیْنَ یَصِلُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰہُ بِہٖ اَنْ یُّوْصَلَ (الرعد:ع ۳)
۹۔ رَبَّنَا اغْفِرْلِیْ وَلِوَالِدَیَّ (إبراھیم: ع ۶)
۱۰۔ وَبِالْوَالِدَیْنِ اِحْسَانًا (بني إسرائیل: ع ۳)
۱۱۔ وَاخْفِضْ لَھُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ (بني إسرائیل: ع ۳)
۱۲۔ وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰی حَقَّہٗ (بني إسرائیل: ع ۳)
۱۳۔ وَکَانَ تَقِیًّاo وَّبَرًّا بِوَالِدَیْہِ (مریم: ع۱)
۱۴۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِیْ (مریم:ع۲)
۱۵۔ اِذْ قَالَ لِاَبِیْہِ یٰٓـاَبَتِ الآیۃ (مریم: ع۳)
۱۶۔ وَکَانَ یَاْمُرُ اَھْلَہٗ بِالصَّلٰوۃِ وَالزَّکوٰۃِ (مریم: ع۴)
۱۷۔ وَاْمُرْ اَھْلَکَ بِالصَّلٰوۃِ (طٰہٰ: ع ۸)
۱۸۔ وَالَّذِیْنَ یَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا ھَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّیّٰتِنَا (الفرقان: ع ۶)
۱۹۔ وَاَصْلِحْ لِیْ فِیْ ذُرِّیَّتِیْ (الأحقاف: ع ۲)
۲۰۔ رَبِّ اغْفِرْلِیْ وَالِوَالِدَیَّ (نوح: ع ۲)
یہ چند آیات نمونہ کے طور پر ذکر کی گئیں کہ سب کے لکھنے میںاورترجمہ میں طول کا ڈر تھا۔ یہ ان تین آیات کے علاوہ ہیں جو مفصل یہاں ذکر کی گئیں۔ ان کے علاوہ اوربھی آیات ملیںگی۔ جس چیز کو اللہ نے اپنے پاک کلام میں بار بار ارشاد فرمایا ہو اس کی اہمیت کاکیاپوچھنا۔ حضرت کعب احبار ؒ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس پاک ذات کی جس نے سمندر کو حضرت موسیٰ ؑ اور بنی اسرائیل کے لیے دو ٹکڑے کر دیا تھا! تورات میں لکھا ہے کہ اللہ سے ڈرتا رہ اور صلۂ رحمی کرتا رہ، میں تیری عمر بڑھا دوں گا، سہولت کی چیزوں میں تیرے لیے سہولت پیدا کر دوں گا، مشکلات کو دور کر دوں گا۔
حق تعالیٰ شا نہٗ نے قرآن پاک میں کئی جگہ صلۂ رحمی کا حکم کیا ہے۔ چناں چہ ارشاد ہے: { وَاتَّقُوْا اللّٰہَ الَّذِیْ تَسَآئَ لُوْنَ بِہٖ وَالْاَرْحَامَ} (النساء : ع ۱)’’ یعنی اللہ تعالیٰ شا نہٗ سے ڈرتے رہو جس سے کہ اپنی حاجت طلب کرتے ہو اور رِشتوں سے ڈرتے رہو۔‘‘ یعنی ان کو جوڑتے رہو توڑو نہیں۔ دوسری آیت میں ارشاد ہے: { وَاٰتِ ذَاالْقُرْبٰی حَقَّہٗ } ’’یعنی رشتہ دار کا جو حق نیکی اور صلۂ رحمی کا ہے وہ ادا کرتے رہو۔‘‘ تیسری جگہ ارشاد ہے: { اِنَّ اللّٰہَ یَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ} ’’یعنی اللہ توحید کا اور لَا إِلٰہَ إِلَّا اللّٰہُ کی شہادت کا حکم فرماتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کا اور ان سے درگزر کرنے کا حکم فرماتے ہیں، اور رشتہ داروں کو دینے کا یعنی صلۂ رحمی کا حکم فرماتے ہیں۔‘‘ تین چیزوں کا حکم فرمانے کے بعد تین چیزوں سے منع کیا ہے۔ فحش سے یعنی گناہ سے، اور منکر سے یعنی ایسی بات سے جس کی شریعت میں اورسنت میں اصل نہ ہو، اور ظلم سے یعنی لوگوں پر تعلّی سے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی تم کو نصیحت فرماتے ہیں تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔
حضرت عثمان بن مظعونؓ فرماتے ہیں کہ حضورﷺسے مجھے بہت محبت تھی اور اسی کی شرم میں مسلمان ہوا تھا کہ حضورﷺمجھ سے مسلمان ہونے کو فرماتے تھے۔ اس وجہ سے میں مسلمان ہوگیا، لیکن اسلام میرے دل میں نہ جما تھا۔ ایک مرتبہ میں حضورﷺ کے پاس بیٹھا ہوا کچھ باتیں کر رہا تھا کہ مجھ سے باتیں کرتے کرتے حضورﷺکسی دوسری طرف ایسے متوجہ ہوگئے جیسے کسی اور سے باتیں کر رہے ہوں۔ تھوڑی دیر میں پھر میری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرئیل ؑ آئے تھے اور یہ آیتِ شریفہ: { اِنَّ اللّٰہَ یَاْمُرُ بِالْعَدْلِ} آخرتک نازل ہوئی۔ مجھے اس مضمون سے بہت مسرت ہوئی اور اسلام میرے دل میں جم گیا۔ میں وہاں سے اٹھ کر حضورﷺ کے چچا ابو طالب کے پاس گیا (جومسلمان نہ تھے) ا ن سے جاکر میں نے کہا کہ میں تمہارے بھتیجے کے پاس تھا، ان پر اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ وہ کہنے لگے کہ محمد (ﷺ) کا اِتباع کرو فلاح کوپہنچو گے۔ خدا کی قسم! وہ اپنی نبوت کے دعویٰ میں سچے ہوں یا جھوٹے، لیکن تمہیں تو اچھی عادتوں کی ہی تعلیم اور کریمانہ اخلاق سکھاتے ہیں۔ (تنبیہ الغافلین) یہ ایسے شخص کی نصیحت ہے جو خود مسلمان بھی نہیں ہیں کہ وہ بھی اس کا اقرار کرتے ہیں کہ نبوت کا دعویٰ سچا ہو یا جھوٹا لیکن اسلام کی تعلیم بہترین تعلیم ہے، وہ کریمانہ اخلاق سکھاتی ہے، مگر افسوس کہ آج ہم مسلمانوں ہی کے اخلاق سب سے زیادہ گرے ہوئے ہیں۔
۲۔ وَلَا یَاْتَلِ اُولُوْا الْفَضْلِ مِنْکُمْ وَالسَّعَۃِ اَنْ یُّؤْتُوْآ اُولِیْ الْقُرْبٰی وَالْمَسٰکِیْنَ وَالْمُھٰجِرِیْنَ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰہِ ص وَلْیَعْفُوْا وَلْیَصْفَحُوْا ط اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ یَّغْفِرَ اللّٰہُ لَکُمْ ط وَاللّٰہُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌo (النور : ع۳)
یہ آیتِ شریفہ اور اس کاترجمہ پہلی فصل کے نمبر (۱۸) پر گزر چکا ہے ۔ مجھے اس کے اِعادہ سے اس پر تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ ہم لوگ اپنے ان اَسلاف کے معمولات پربھی غور کریں اور حق تعالیٰ شا نہٗ کی اس ترغیب پر بھی۔ کتنا سخت اور اہم واقعہ ہے کہ حضور ﷺکی بیوی، سارے مسلمانوں کی ماں، ان پر اولاد کی طرف سے بے بنیاد تہمت لگائی جائے اور اس کو پھیلاتے وہ قریبی رشتہ دار ہوں جن کا گزر اوقات بھی ان کے باپ ہی کی اِعانت پر ہو، اس پر باپ یعنی حضرت ابوبکر صدیقؓکو جس قدر بھی رنج اور صدمہ ہو وہ ظاہر ہے، اس پر اللہ کی طرف سے یہ ترغیب کہ معاف کریں اور درگزر کریں، اور حضرت صدیقًؓؐ کی طرف سے یہ عمل کہ جتنا پہلے خرچ کرتے تھے اس میں اضافہ فرمایا، جیسا کہ پہلے گزر چکا،کیا ہم بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ایسا معاملہ کرسکتے ہیں کہ کوئی ہم پر الزام رکھے، ہمارے گھر والوں کو ایسی سخت چیز کے ساتھ متہم کرے، اور پھر ہم قرآنِ پاک کی اس آیتِ شریفہ کو تلاوت کریں اور اس رشتہ دار کی قرابت پر نگاہ رکھتے ہوئے کسی قسم کی اِعانت اس کی گوارہ کرلیں؟ حاشا وکلَّا! عمر بھر کی اسی سے نہیں اس کی اولاد سے بھی دشمنی بندھ جائے گی، بلکہ جو دوسرے رشتہ دار اس سے تعلق رکھیں گے ان کا بھی بائیکاٹ کر دیں گے اور جس کسی تقریب میں وہ شریک ہوں گے مجال ہے کہ ہم اس میں شرکت کرلیں۔ کیوں؟ فقط اس لیے کہ یہ لوگ ایسے شخص کی تقریب میںیا دعوت میں شریک ہوگئے جس نے ہمیں گالی دے دی، ہماری آبرو گرادی، ہماری بہو بیٹی پر تہمت لگا دی، چاہے لوگ اس گالی دینے والے کے فعل سے کتنے ہی ناراض ہوں، مگر اس کی تقریب میں شرکت کے جرم میں ان سے بھی ہمارا قطع تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پاک ارشاد یہ ہے کہ ہم خود بھی اس کی اِعانت سے ہاتھ نہ روکیں اورہمارا عمل یہ ہے کہ کوئی دوسرا بھی اس کی دعوت کر دے تو ہم اس دوسرے سے بھی تعلقات منقطع کر دیں، لیکن جن کے دل میں حقیقی ایمان ہے، اللہ کی عظمت ان میں راسخ ہے، اس کے پاک ارشاد کی ان کو وقعت ہے، انھوںنے اس پرعمل کر کے دکھا دیا کہ اطاعت کرنا اس کو کہتے ہیں، مطیع ایسے ہوتے ہیں۔ اللہ اپنے عالی شان کے موافق ان پر رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے شان کے موافق ان کے درجات بلند فرمائے۔ آخر یہ بھی جذبات رکھتے تھے، غیرت حمیّت رکھتے تھے، ان کے سینوں میں دل اور اس میں جذبات بھی تھے،لیکن اللہ کی رضا کے سامنے کیسا دل اورکہاں کے جذبات؟ کیسی غیرت اورکہاں کی بدنامی؟ اللہ کی رضا کے مقابلہ میں سب چیز فنا تھی۔
۳۔ وَوَصَّیْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَیْہِ اِحْسَانًاط حَمَلَتْہُ اُمُّہٗ کُرْھًا وَّوَضَعَتْہُ
اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا۔ (بالخصوص
کُرْھًا ط وَحَمْلُہٗ وَ فِصَالُہٗ ثَلٰـثُوْنَ شَھْرًاط حَتّٰی اِذَا بَلَغَ اَشُدَّہٗ وَ بَلَغَ اَرْبَعِیْنَ سَنَۃً قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِیْ ٓ اَنْ اَشْکُرَ نِعْمَتَکَ الَّتِیْ اَنْعَمْتَ عَلَیَّ وَعَلٰی وَالِدَیَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰہُ وَاَصْلِحْ لِیْ فِیْ ذُرِّیَّتِیْ ط اِنِّیْ تُبْتُ اِلَیْکَ وَاِنِّیْ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ o اُولٰٓئِکَ الَّذِیْنَ نَتَقَبَّلُ عَنْھُمْ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَ نَتَجَاوَزُ عَنْ سَیِّاٰتِھِمْ فِیٓ اَصْحَابِ الْجَنَّۃِ ط وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِیْ کَانُوْا یُوْعَدُوْنَ o (الأحقاف: ع ۲)
ماں کے ساتھ احسان کا اور بھی زیادہ، کیوںکہ) اس کی ماںنے بڑی مشقت کے ساتھ اس کوپیٹ میںرکھا اور بڑی مشقت سے اس کو جنا، اور اس کو پیٹ میں رکھنے اور دودھ چھڑانے میں (اکثر کم سے کم) تیس مہینے ہو جاتے ہیں، (کتنی طویل مشقت ہے) یہاںتک کہ جب وہ بچہ جوان ہوتا ہے، (اور دانائی کے زمانہ) چالیس برس کو پہنچتا ہے تو (جو سعید ہوتا ہے وہ) کہتاہے: اے میرے پروردگار! مجھے اس پر مداومت دیجیے کہ میں ان نعمتوں کا
شکر ادا کروں جو آپ نے مجھ کو اور میرے والدین کو عطا فرمائیں، اور( اس کی توفیق دیجیے کہ) میںا یسے نیک کام کیا کروں جن سے آپ راضی ہوجائیں اور میری اولاد میں بھی میرے (نفع کے) لیے صلاحیت پیدا فرما دیں۔ میں (اپنے سارے گناہوں سے) توبہ کرتا ہوں اور میں آپ کے فرماںبرداروں سے ہوں۔ (آگے حق تعالیٰ شا نہٗ ان لوگوں کے متعلق فرماتے ہیں کہ) یہی لوگ ہیں جن کے نیک کاموں کو ہم قبول کرلیں گے اور ان کی برائیوں سے درگزر کریں گے اس طرح پر کہ یہ جنت والوں میں سے ہوں گے، یہ اس وعدہ کی وجہ سے ہے جس کاان سے دنیا میں وعدہ کیا جاتا تھا (کہ نیک اعمال کا صلہ جنت ہے)۔
فائدہ: حق تعالیٰ شا نہٗ نے اہلِ قرابت اور والدین کے بارے میں بار بار تاکید فرمائی جیسا کہ پہلی آیتِ شریفہ کے ذیل میں گزر چکا۔ اس آیتِ شریفہ میں خاص طور سے والدین کے بارے میں احسان کی خصوصی تاکید فرمائی کہ ہم نے والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا ہے۔ یہ مضمون اسی عنوان سے کہ ہم نے والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا، تین جگہ قرآنِ پاک میں وارد ہے۔ پہلی جگہ سورئہ عنکبوت رکوع ( ۱ ) میں، پھر سورۂ لقمان رکوع (۲)میں، تیسری جگہ یہاں جس سے بہت زیادہ تاکید معلوم ہوتی ہے۔
صاحب ’’ِخازن‘‘ نے لکھا ہے کہ یہ آیتِ شریفہ حضرت ابوبکر صدیقؓکی شان میں نازل ہوئی کہ اِبتداء ًا ان کی رفاقت حضورِ اقدسﷺ کے ساتھ شام کے سفر میں ہوئی تھی جب کہ ان کی عمر اٹھارہ سال کی تھی اور حضورﷺکی عمر شریف بیس سال کی تھی۔ اس سفر میں راستہ میں ایک بیری کے درخت کے پاس ان دونوں کا قیام ہوا۔ حضرت ابوبکرؓ وہاں ایک راہب تھا اس سے ملنے تشریف لے گئے اور حضورﷺ درخت کے سایہ میں تشریف فرما رہے۔ اس راہب نے حضرت ابوبکرؓ سے پوچھا کہ یہ شخص جو درخت کے نیچے ہے کون ہے؟ آپ نے فرمایا: محمد بن عبداللہ بن عبدالمطّلب۔ راہب نے کہا: خدا کی قسم! یہ نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ و السلام کے بعد سے اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھا، یہی نبی ٔ آخر الزماںہیں۔ جب حضورﷺکی عمر شریف چالیس سال کی ہوئی اور آپ کو نبوت ملی تو حضرت ابوبکر صدیقؓ مسلمان ہوئے اور دو برس بعد جب آپ کی عمر چالیس سال کی ہوئی تو یہ دعا کی: رَبِّ اَوْزِعْنِیْ کہ مجھے توفیق دیجیے کہ میںاس نعمت کا شکر ادا کروں جو مجھ پر اور میرے والدین پرہوئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ یہ فضیلت مہاجرین میں کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی کہ اس کے ماں باپ دونوں مسلمان ہوئے ہوں۔ اور دوسری دعا اولاد کے متعلق صلاحیت کی فرمائی جس کا ثمرہ یہ ہے کہ آپ کی اولاد بھی مسلمان ہوئی۔ (تفسیرِخازن)
سب سے پہلی آیت سورئہ عنکبوت والی اور بھی زیادہ سخت ہے کہ اس میں ان والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم ہے جو کافر ہوں۔ اور جب کافر والدین کے ساتھ بھی حق تعالیٰ شا نہٗ کی طرف سے اچھا برتائو اور بھلائی کرنے کا حکم ہے تو مسلمان والدین کے ساتھ بھلائی اور احسان کی تاکید بطریقِ اولیٰ ہے۔
حضرت سعد بن ابی وقّاصؓ فرماتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا تو میری ماں نے یہ عہد کرلیا کہ میں نہ کھانا کھائوں گی نہ پانی پیئوں گی، جب تک کہ تُو محمد(ﷺ) کے دین سے نہ پھرے گا۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا،حتیٰ کہ زبردستی اس کے منہ میں ڈالا جاتا تھا۔ اس پر یہ آیتِ شریفہ نازل ہوئی۔ (دُرِّمنثور) عبرت کامقام ہے کہ ایسی سخت حالت میں بھی اللہ پاک کاارشاد ہے کہ ہم نے آدمی کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا ہے۔ البتہ اگر وہ مشرک بنانے کی کوشش کریں تو اس میں اطاعت نہیں ہے۔ حضرت حسن ؒ سے کسی نے پوچھا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی کیا مقدار ہے؟ انھوںنے فرمایا کہ جو کچھ تیری مِلک میں ہے ان پرخرچ کرے اورجو وہ حکم کریں اس کی اطاعت کرے، بجز اس کے کہ وہ کسی گناہ کا حکم کریں کہ اس میں اطاعت نہیں ہے۔
یہ تھی اسلام کی تعلیم، مسلمانوں کا عمل، کہ مشرک والدین اگر اولاد کو مشرک بنانے کی کوشش بھی کریں تب بھی ان کے ساتھ بھلائی کاحکم ہے۔ البتہ شرک کرنے میں ان کی اطاعت اور فرماںبرداری نہیں، اس لیے کہ یہ خالق کا حق ہے۔ والدین کا حق خواہ کتنا ہی کیوں نہ ہو جائے مالک کے حق کے مقابلہ میں کسی کا حق نہیں ہے۔ لَا طَاعَۃَ لِلْمَخْلُوْقِ فِيْ مَعْصِیَۃِ الْخَالِقِ۔ ’’خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں‘‘۔
لیکن ان کے اس حکم اور اولاد کو مشرک بنانے کی کوشش پر بھی ان کے ساتھ احسان کا، بھلائی کا حکم ہے۔ ایک اور حدیث میںسورئہ لقمان والی آیت کے متعلق وارد ہوا ہے کہ یہ حضرت سعد ؓ کے واقعہ میں نازل ہوئی۔ اس حدیث میں ہے حضرت سعدؓ فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ بہت سلوک کیاکرتا تھا۔ جب میں مسلمان ہوگیا تومیری والدہ نے کہا: سعد! یہ کیا کیا؟ یا تواس دین کو چھوڑ دے ورنہ میں کھانا چھوڑ دوںگی یہاں تک کہ مرجائوں گی، ہمیشہ تیرے لیے یہ طعن کی چیز رہے گی، لوگ تجھے اپنی ماں کا قاتل کہیں گے۔ میں نے اس سے کہا کہ ایسا نہ کر، میں اپنا دین توچھوڑ نہیں سکتا۔ اُس نے ایک دن بالکل نہ کھایا نہ پیا۔ دوسرا دن بھی اسی حال میں گزرگیا، تو میں نے اس سے کہا کہ اگر تمہاری سو جانیں ہوں اور ایک ایک کرکے سب ختم ہو جائیں، تب بھی دین تو نہیں چھوڑ سکتا۔ جب اس نے یہ پختگی دیکھی تو کھانا پینا شروع کر دیا۔ (دُرِّمنثور)
اس آیتِ شریفہ میں والدین کے ساتھ نیک سلوک کا حکم ہے۔ فقیہ ابوللیث ؒ فرماتے ہیں کہ اگر حق تعالیٰ شا نہٗ والدین کے حق کا حکم نہ بھی فرماتے تب بھی عقل سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کا حق بہت ضروری اور اہم ہے، چہ جائے کہ اللہ نے اپنی سب کتابوں تورات، انجیل، زبور، قرآنِ شریف میں ان کے حق کا حکم فرمایا۔ تمام انبیائے کرام ؑ کو ان کے حق کے بارے میں وحی بھیجی اور تاکید فرمائی۔ اپنی رضا کو والدین کی رضا کے ساتھ وابستہ کیا اور ان کی ناراضی پر اپنی ناراضی مرتب فرمائی۔ (تنبیہ الغافلین)
یہ تین آیات حسنِ سلوک کے متعلق تھیں، اس کے بعد صرف تین آیات بدسلوکی پر تنبیہ کے متعلق بھی ذکر کرتا ہوں۔
۱۔ وَمَا یُضِلُّ بِہٖٓ اِلاَّ الْفٰسِقِیْنَ o الَّذِیْنَ یَنْقُضُوْنَ عَھَدَ اللّٰہِ مِنْم بَعْدِ مِیْثَاقِہٖ وَیَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰہِ بِہٖ اَنْ یُّوْصَلَ وَیُفْسِدُوْنَ فِی الْاَرْضِط اُوْلٰٓئِکَ ھُمُ الْخٰسِرُوْنَ o (البقرۃ:ع۳)
اور نہیں گمراہ کرتے اللہ تعالیٰ شا نہٗ اس مثال سے (جس کا پہلی آیت میں ذکر ہوا)، مگر ایسے فاسق لوگوں کو جو توڑتے رہتے ہیں اس معاہدہ کو جو اللہ تعالیٰ سے کرچکے تھے اس معاہدہ کی پختگی کے بعد۔ اورقطع کرتے
رہتے ہیں ان تعلقات کو جن کے وابستہ رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ اور فساد کرتے رہتے ہیں زمین میں۔ یہی لوگ ہیں پورے خسارہ والے۔
فائدہ: جیسا کہ اللہ نے قرآنِ پاک میںکئی جگہ صلۂ رحمی بالخصوص والدین کے حقوق کی رعایت کا حکم اور ترغیب فرمائی، جیساکہ اوپرگزرا، اسی طرح سے بہت سی جگہ اپنے پاک کلام میں قطعِ رحمی بالخصوص والدین کے ساتھ بدسلوکی پر بھی تنبیہ فرمائی۔ پہلے کی طرح ان میں سے بھی چند آیات کا حوالہ لکھتا ہوں۔ دوستو! غور کرو، اللہ کے پاک کلا م میں جب بار بار اس پر تنبیہ ہے تو اس کو سوچو اور عبرت حاصل کرو۔ اللہ کاپاک ارشاد ہے:
۱۔ وَاتَّقُوْا اللّٰہَ الَّذِیْ تَسَآئَ لُوْنَ بِہٖ وَالْاَرْحَامَ (النساء : ع۱)
۲۔ وَلَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَکُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ (الأنعام :ع ۱۹)
۳۔ وَلَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَکُمْ خَشْیَۃَ اِمْلاَقٍ (بني إسرائیل : ع ۴)
۴۔ وَالَّذِیْ قَالَ لِوَالِدَیْہِ الآیۃ (الأحقاف : ع ۲)
۵۔ اَنْ تُفْسِدُوْا فِی الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا اَرْحَامَکَمْ (محمد : ع۳)
حضرت محمد باقر ؒکو ان کے والد نے جو خاص طور سے اہتمام سے وصیت فرمائی ہے، جو پہلی فصل کی احادیث کے سلسلہ میں نمبر (۲۳) پر بھی گزر چکی ہے، وہ بہت تجربہ کی بات ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد (حضرت امام زین العابدین ؒ) نے وصیت فرمائی ہے کہ پانچ قسم کے آدمیوں کے پاس نہ پھٹکیو، ا ن سے بات نہ کی جیو، حتیٰ کہ راستہ چلتے ہوئے اتفاقًا بھی ان کے ساتھ نہ چلنا۔
اول: فاسق شخص کہ وہ ایک لقمہ کے بدلہ میں تجھ کو بیچ دے گا، بلکہ ایک لقمہ سے کم میں بھی۔ میں نے پوچھا کہ ایک لقمہ سے کم میں کس طرح بیچے گا؟ فرمانے لگے کہ محض لقمہ کی امیدپر تجھ کو بیچ دے گا اور وہ لقمہ اس کو میسر بھی نہ ہوگا۔ نمبر ۲: بخیل کہ وہ تیری سخت احتیاج کے وقت بھی تیرے سے کنارہ کش ہو جائے گا۔ نمبر۳: جھوٹا شخص کہ وہ بالُو (دھوکہ) کی طرح سے تجھے دھوکا میں رکھے گا۔ جو چیز دور ہوگی اس کو قریب بتائے گا، جو قریب ہوگی اس کو دور ظاہر کرے گا۔ نمبر ۴: بے وقوف کے پاس نہ لگنا کہ وہ تجھے نفع پہنچانے کا ارادہ کرے گا تب بھی اپنی حماقت سے نقصان پہنچا دے گا۔ مثل مشہور ہے کہ دانا دشمن نادان دوست سے بہتر ہے۔ نمبر۵: قطع رحمی کرنے والے کے پاس نہ جائیو کہ میں نے قرآنِ پاک میں تین جگہ اس پر اللہ کی لعنت پائی ہے۔ (روض الریاحین)
۲۔ وَالَّذِیْنَ یَنْقُضُوْنَ عَھْدَ اللّٰہِ مِنْ بَعْدِ مِیْثَاقِہٖ وَ یَقْطَعُوَْنَ مَآ اَمَر َاللّٰہُ بِہٖ اَنْ یُّوْصَلَ وَیُفْسِدُوْنَ فِیْ الْاَرْضِط اُولٰٓئِکَ لَھُمُ اللَّعْنَۃُ وَلَھُمْ سُوٓئُ الدَّارِo (الرعد : ع ۳)
اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے معاہدہ کو اس کی پختگی کے بعد توڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جن تعلقات کے جوڑنے کا حکم فرمایا ان کو توڑتے ہیں، اور دنیا میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر لعنت ہے اور ان کے لیے اس جہان میں خرابی ہے۔
فائدہ: حضرت قتادہ ؒ سے نقل کیا گیا کہ اس سے بہت احتراز کرو کہ عہد کرکے توڑ دو۔ اللہ نے اس کو بہت ناپسند کیا ہے اور بیس آیتوں سے زائد میں اس پر وعید فرمائی ہے، جو نصیحت کے طور پر اور خیر خواہی کے طور پر اور حجت قائم کرنے کے لیے وارد ہوئی ہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ اللہ نے عہدکے توڑنے پر جتنی وعیدیں فرمائی ہیں اس سے زائد کسی اور چیز پرفرمائی ہوں۔ پس جو شخص اللہ کے واسطہ سے عہد کرلے اس کو ضرور پورا کرے۔ حضرت انس ؓ فرماتے ہیں کہ حضورِ اقدسﷺ نے خطبہ میں فرمایا کہ جو شخص امانت کو واپس نہ کرے اس کاایمان ہی نہیں اور جو عہد کو پورا نہ کرے اس کا دین نہیں۔ حضرت ابو امامہ اور حضرت عبادہ ? سے بھی یہ مضمون نقل کیا گیا۔ (دُرِّمنثور)
حضرت میمون بن مہران ؒ فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں کافر مسلمان کی کوئی تفریق نہیں، سب کا حکم برابر ہے۔ اوّل جس سے معاہدہ کیا جائے اس کو پورا کیا جائے، چاہے وہ معاہدہ کافر سے کیا ہو یا مسلمان سے۔ اس لیے کہ عہد حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے ہے۔ دوسرے جس سے رشتہ کا تعلق ہو اس کی صلۂ رحمی کی جائے، چاہے وہ رشتہ دار مسلمان ہو یا کافر۔ تیسرے جو شخص امانت رکھوائے اس کی امانت واپس کی جائے، امانت رکھوانے والا مسلمان ہو یا کافر ہو۔ (تنبیہ الغافلین)
قرآن پاک میں بہت سی آیات کے علاوہ ایک جگہ خاص طور سے اسی کا حکم ہے:
{وَاَوْفُوْا بِالْعَھْدِج اِنَّ الْعَھْدَ کَانَ مَسْئُوْلاًo} (بني إسرائیل: ع۴)






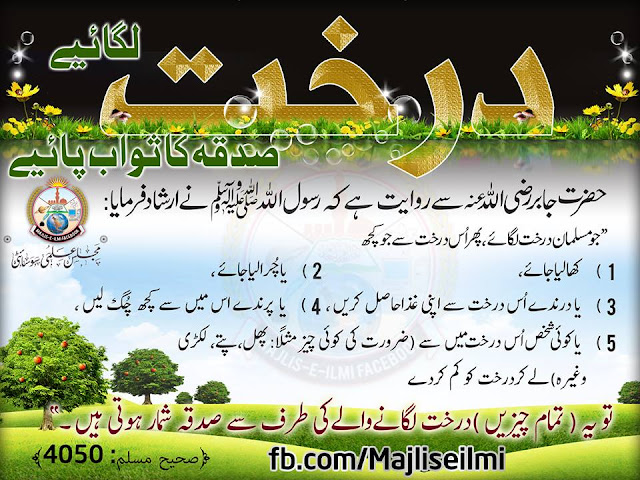








































No comments:
Post a Comment